قرآن کریم میں تناقض پائے جانے کا وهم و گمان
بعض انٹرنٹ کی معلوم الحال سایٹوں پر ایک مدت سے ”قرآن کریم کی ساٹھ مشکلیں اور تناقض“ کے عنوان سے کچھ مطالب نظر آرہے ہیں بہت سے لوگ (منظم کمیٹیوں کی شکل میں) ان مطالب کو بہت وسیع پیمانہ پر مسلمانوں کو ایمیل کے ذریعہ بھیج رہے ہیں ،بہت سے مخصوص ڈش ٹی وی بھی مسلمانوں کے عقیدہ اورایمان کو کمزور کرنے کیلئے شک و شبہات ڈالنے میں مشغول ہیں اور ہر سال ماہ رمضان کی آمد پر جو کہ قرآن کریم کی بہار ہے، ان توہمات ،شکوک اور جھوٹی باتوں کو منتشر کرنے میں پوری کوشش کرتے ہیں ۔

یہ لوگ ایسے شبہات کو نشر کرتے ہیں جن کا علماء قرآن اور محققین بارہا جواب دے چکے ہیں ،ان میں سے بعض شبہات بہت ہی سادہ ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سوالوں کو بنانے والے کا علم ، قرآن اور علوم قرآن کی بانسبت بہت کم ہے ، بہت سے شبہات فقط تہمتیں اور الزامات ہیں جن سے قرآن کریم منزہ ہے ۔ اکثر و بیشتر شبہات ایسے ہیں جن کو عربی کی سایٹوں سے ترجمہ کیا گیا ہے اور وہ سایٹیں افراطی عیسائیوں کے گروہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان شبہات کا سرچشمہ ان مستشرقین کی فکروں کا نتیجہ ہے جو چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت کو اپنی تحریف شدہ (یہودیوں اور عیسائیوں کی) کتابوں کی حد تک نیچے لے آئیں ۔
ہم نے اس مقالہ میں ان شک و شکوک کی تحقیق کریں گے جن کے متعلق بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ ان کو نشر کرنے سے قرآن کریم کی قداست اور حقانیت کو کم کردیں گے ۔
قرآن کریم میں تناقض کا نہ ہونا
خداوند عالم نے سورہ شوری میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے فرمایا ہے : ” اٴَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّا“ (۱)۔ اور ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی بھیجی ۔
سورہ نجم میں کہا ہے :”وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْہَوی ، إِنْ ہُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحی“ (۲)۔ اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے ،اس کا کلام وہی وحی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے ۔
دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آ لہ وسلم) صرف خداوند عالم کے حکم کو پہنچانے والے تھے اوراس میں کسی قسم کی کمی و زیادتی کا حق نہیں تھا ، آپ کو نہ قرآن کریم کی آیات میں تصرف کرنے کا حق تھا اور نہ ہی آپ اس طرح کا کوئی قصدکرسکتے تھے ۔خداوند عالم نے سورہ ”حاقہ“ میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے متعلق چیلنج کیا ہے اور کہا ہے : ”وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْاٴَقاویلِ ، لَاٴَخَذْنا مِنْہُ بِالْیَمینِ ، ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْہُ الْوَتینَ“(۳) ۔ اور اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا ، تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور پھر اس کی گردن اڑادیتے ۔
ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی وحی ہے اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) صرف پہنچانے والے ہیں ۔ یہی بات سبب بنی کہ قرآن کریم میں کسی قسم کا کوئی اختلاف اورتناقض نہیں ہے اور یہ کتاب ہر طرح کی کجی اور باطل سے خالی ہے ۔ خداوند عالم نے قرآن کریم کی اس خصوصیت کے متعلق سورہ ”زمر“ میں اشارہ کیا ہے اور کہا ہے : ”قُرْآناً عَرَبِیًّا غَیْرَ ذی عِوَجٍ “(۴) ۔ یہ عربی زبان کا قرآن ہے جس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے ۔”لا یَاٴْتیہِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَ لا مِنْ خَلْفِہِ “(۵) ۔ جس کے قریب سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آبھی نہیں سکتا ہے ۔
اگر قرآن کو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے علاوہ کوئی اور انسان لاتا تو اس میں اختلاف اورتناقض ہوتاکیونکہ انسان پوری زندگی میں اپنی فکر کو کامل کرتا رہتا ہے اوران کے افکار تبدیل ہوتے رہتے ہیں ،کیا ممکن ہے کہ انسان کی پوری زندگی میں اس کے شخصی افکار میں بیس دفعہ سے زیادہ تبدیلی واقع نہ ہو ؟ اوراس کی تمام باتیں اس پوری زندگی میں اشتباہ اور تناقص سے خالی ہوں ۔
اس بناء پر جب ہم قرآن کریم میں غوروفکر کرتے ہیں اور آیات الہی کو اختلاف اور تناقض سے خالی پاتے ہیں تو یہی قرآن کریم کے وحی ہونے کی دلیل ہے ۔ خداوند عالم نے اس استدلال کی طرف سورہ نساء میں اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے : ”اٴَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّہِ لَوَجَدُوا فیہِ اخْتِلافاً کَثیراً“(۶) ۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا ۔
اس آیت میں دو نکتہ پوشیدہ ہیں :
۱۔ قرآن کریم میں اختلاف اور تناقص نہیں ہے ۔
۲۔ قرآن کریم ، اللہ کی طرف سے وحی ہے ۔
معصومین (علیہم السلام) کی احادیث میں بھی قرآن کریم میں اختلاف، باطل اور کجی نہ ہونے کی طرف اشارہ ہوا ہے :
۱۔ امیرالمومنین علی (علیہ السلام) نے فرمایا : ”علیکم بکتاب اللہ ! فانہ الحبل المتین ․․․ لا یعوج فیقام ، و لا یزیغ فیستعتب “ (۷) ۔
تمهارا فریضہ ہے کہ کتاب خدا سے وابستہ رہو کہ وہی مضبوط ریسمان ہدایت اور روشن نور الہی ہے…. اس میں کوئی کجی نہیں ہے جسے سیدها کیا جائے اور اس میں کوئی انحراف نہیں ہے جسے درست کیا جائے
۲۔ امام سجاد (علیہ السلام) فرماتے ہیں : ” ․․․ و میزان قسط لا یحیف عن الحق لسانہ، و نور ھدی لا یطفا عن الشاھدین برھانہ “ (۸) ۔ قرآن کریم ایسی صحیح ترازو ہے جس کے پلہ حق سے منحرف نہیں ہوتے اور ایسی ہدایت کا نور ہے جس کا فروغ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے محو نہیں ہوتا ۔
۳۔ امام صادق (علیہ السلام) نے فرمایا : ”ھو قول اللہ و تنزیلہ ، و ھو الکتاب العزیز الذی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ ، تنزیل من حکیم حمید“ (۹) ۔
قرآن کریم اللہ کا کلام اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور ایسی عزیز کتاب ہے جس کے قریب، سامنے یا پیچھے کسی بھی طرف سے باطل آبھی نہیں سکتا ہے اور یہ خداوندعالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے ۔
اس بناء پر اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین کیلئے ہدایت ہے ۔ ” ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین “ ۔
معصومین (علیہم السلام) کے زمانہ میں قرآن کریم میں تناقض کے وہم و گمان کی تاریخ
اس بات کومدنظر رکھتے ہوئے کہ ہر پیغمبر اپنی نبوت کو ثابت کرنے کیلئے معجزہ پیش کرتا تھا اس لئے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے بھی قرآن کریم کو معجزہ الہی کے طور پر پیش کیا ۔ ایسا معجزہ جو دلوں پر اثر اندا زہوتا تھا اوراس کا اثر تمام مشرکوں پرپوشیدہ نہیں تھا ۔ لہذا اسی زمانہ سے آپ کے دشمن قرآن کریم کی حقیقت کو چھپانے اور لوگوں کے دلوں پر قرآن کریم کی آیات کے اثر کوباطل کرنے کی کوشش کرتے تھے ۔ لیکن ان کی کمزوری اور لوگوں کے قرآن کریم کو سننے کے استقبال کی وجہ سے مشرکوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ قرآن کریم سننے پر پابندی لگادی جائے ، لوگوں اور مکہ کے مسافروں کو سننے سے منع کیا جائے ۔
لہذا انہوں نے لوگوں میں خوف و وحشت ایجاد کرنے اور لوگوں کوپیغمبر اکرم(صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے دور کرنے کیلئے آنحضرت (ص) پر الزامات لگائے ۔ انہوں نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کو نعوذ باللہ دیوانہ (۱۰) ، کاھن (۱۱) ، شاعر (۱۲) اور کاذب (۱۳) وغیرہ کہنا شروع کردیا ، اس کے علاوہ یہ لوگ قرآن کریم کو افسانہ اور قدیمی کہانیاں (۱۴) کہتے تھے ۔
ائمہ (علیہم السلام) کے زمانہ میں بھی قرآن کریم کی تعلیمات کے رائج اور منتشر ہونے کی وجہ سے قرآن پر تہمتیں ، الزام لگائے جاتے تھے اور خدا کے کلام ہونے کا انکار کرتے تھے ۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کے دلوں میں شک و شکوک ایجاد ہونے لگے ۔ قرآن کریم کے تناقضات کے سوالوں کے متعلق ائمہ (علیہم السلام) اور ان کے اصحاب کے جواب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں یہ شبہات پائے جاتے تھے ہم یہاں پر ان میں سے بعض شکوک کی طرف اشارہ کریں گے :
۱۔ شیخ صدوق کی کتاب توحید میں ”الرد علی الثنویة و الزنادقة“ کے باب میں نقل ہوا ہے کہ ایک شخص امیرالمومنین علی (علیہ السلام) کے پاس آیا اورعرض کیا : ”انی قد شککت فی کتاب اللہ المنزل “ ۔ مجھے اللہ کی کتاب میں شک ہوگیا ہے ۔ جس وقت امام علیہ السلام نے اس کی وجہ معلوم کی تو کہا : ”لانی وجدت الکتاب یکذب بعضہ بعضا فکیف لا اشک فیہ“ : کیونکہ بعض آیات دوسری آیات کی تکذیب کرتی ہیں ، پھر اس میں کیوں شک نہ کروں ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا : ”ان کتاب اللہ لیصدق بعضہ بعضا ولا یکذب بعضہ بعضا و لکنک لم ترزق عقلا تنتفع بہ ، فھات ما شککت فیہ من کتاب اللہ عزوجل “ ۔ قرآن کریم کی آیات دوسری آیات کی تصدیق کرتی ہیں ، تکذیب نہیں کرتیں ۔ لیکن تیری عقل چھوٹی ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی ، لہذا قرآن کریم کی جس آیت میں تجھے شک ہوا ہے اس کوبیان کر، اپنے شکوک کے موارد کو بیان کر(تاکہ میں اس کے جواب دوں) ۔ اس نے بہت سی آیات شک وشکوک کی بنیاد پر بیان کیا اور امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ۔ اس حدیث میں بہت سے شبھات اور وہ آیتیں جن کے بارے میں تناقض کا وہم ہے ،بیان ہوئی ہیں (۱۵)۔
۲۔ ایک شخص امیرالمومنین (علیہ السلام) کے پاس آیا اور کہا : ” لولا ما فی القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت فی دینکم “ ۔ اگر تمہارے قرآن کریم میں اختلاف اور تناقض نہ ہوتا تو یقینا میں تمہارے دین میں داخل ہوجاتا ۔ امام علیہ السلام) نے فرمایا : کس جگہ اختلاف اورتناقض ہے ؟ اس نے وہ آیتیں بتائی اور امام علیہ السلام نے اس کے جواب دئیے ۔ جس وقت اس کے شبہات ختم ہوگئے تو اس نے اسلام قبول کرلیا ۔ یہ حدیث بہت ہی جامع حدیث ہے جس میں بہت سے شبہات اور وہ آیتیں جواب کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں جن میں تناقض کا وہم کیا جاتا تھا اور مرحوم طبرسی نے اس حدیث کو کتاب ”الاحتجاج علی اھل اللجاج“ میں نقل کیا ہے (۱۶) ۔
۳۔ اصبغ بن نباتہ سے نقل ہوا ہے کہ امیرالمومنین (علیہ السلام) نے کوفہ کے منبر پر حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا : اے لوگو ! مجھ سے سوال کرو کیونکہ میرے اطراف وجوانب میں علم بہت زیادہ ہے ․․․․ ایک شخص نے کہا : ” یا امیرالمومنین وجدت کتاب اللہ ینقض بعضہ بعضا“ ۔ یا امیرالمومنین میں نے بعض آیات میں تناقض پایا ہے ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا : ”کتاب اللہ یصدق بعضہ بعضا ولا ینقض بعضہ بعضا “ ۔ قرآن کریم کی آیات دوسری آیات کی تصدیق کرتی ہیں ، تکذیب نہ کرتی ہیں ۔جو تمہارے ذہن میں فطور کررہا ہے تم اس کو بیان کرو ! اس نے کہا : یا امیرالمومنین ،خداوند عالم نے فرمایا ہے: ”برب المشارق والمغارب “ اور دوسری آیت میں فرمایا ہے : ”رب المشرقین و رب المغربین“ اور ایک جگہ فرمایا ہے : ”رب المشرق والمغرب “ ؟! فرمایا : تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے ! اے ابن کواء یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے ۔ لیکن یہ آیت ” رب المشرقین و رب المغربین “۔ یقینا سردیوں کی مشرق ایک حد پر اور گرمیوں کی مشرق ایک حد پر ہے ،کیا تم اس کو سورج کی نزدیکی اور دوری سے نہیں سمجھتے ؟ لیکن یہ آیت ” رب المشارق والمغارب “ ۔ اس کے تین سو ساتھ برج ہیں ، روزانہ ایک برج میں حاضر ہوتا ہے اور دوسرے برج سے غائب ہوجاتا ہے اورصرف اگلے سال پھر اس برج میں واپس آتا ہے (۱۷ ) ۔
۴۔ ایک شخص نے ابن عباس سے کہا : قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں جن میںاختلاف پایا جاتا ہے ۔ ابن عباس نے اس سے پوچھا کیا تمہیں قرآن کریم میں شک ہے ؟ اس نے کہا : نہیں ۔ پھر اس نے اختلاف والی آیات کو بیان کیا اورابن عباس نے جواب دیا ، اس شخص کا ایک سوال ان آیات کے متعلق تھا جن میں قیامت کے دن کی مقدار کو بیان کیا گیا ہے (۱۸ ) ۔
۵ ۔ نقل ہوا ہے کہ ایک زندیق، امام صادق (علیہ السلام) کی خدمت میں آیا اور اس نے قرآن کریم کی ان آیات ”الرحمن علی العرش استوی“ و ”وسیع کرسیہ السموات والارض“ میں عرش اور کرسی کے بارے میں سوال کیا اورامام علیہ السلام نے اس کو اطمینان بخش جواب دیا (۱۹) ۔
۶۔ ابن اسحاق کندی عراق کا فلسفی تھا اور یہ تیسری صدی میں امام حسن عسکری (علیہ السلام) کے زمانہ میں زندگی بسر کرتا تھا ۔ وہ قرآن کریم کی آیات میں تناقض کے شک کی وجہ سے آیتوں کو جمع کرنے میں مشغول تھا ،اس نے ان آیات کو ایک مجلہ کی شکل میں جمع کیا لہذا جب امام حسن عسکری (علیہ السلام) کو اس کے ایک شاگرد کے ذریعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا : کیا تم اپنے استاد کو اس کام سے منع نہیں کرسکتے ؟ امام نے ابن اسحاق کندی کے ایک شاگرد سے فرمایا : ”جاؤ اور اپنے استاد سے پوچھو : کیا ممکن ہے کہ ایک دن خداوند عالم یہ کہے کہ میں نے قرآن کریم کی آیات کو اس ہدف کے علاوہ دوسرے ہدف کے لئے بھیجا ہے جس کو تم سمجھے ہو ؟ اگر وہ اس بات کو قبول کرلے تو پھر اس سے کہو: اگر ایسا ہے تو تم قرآن کریم کی آیات کے درمیان تناقض کے قائل کس طرح ہوگئے؟۔ شاگرد نے استاد کی خدمت میں یہ باتیں بیان کیں، وہ ان باتوں سے تعجب میں پڑ گیا اور اس نے ایک آگ جلائی اوراپنا لکھا ہوا مجلہ اس میں ڈال دیا (۲۰) ۔
یہ وہ نمونے ہیں جو معصومین (علیہم السلام) کے زمانہ میں ”قرآن کے تناقض “ہونے کے سلسلہ میں بیان ہوئے ہیں اور یہ سوالات بھی عام طور سے زنادقہ کی طرف سے بیان ہوتے تھے اس کے بعد بعض مسلمانوں نے ان کے جوابات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ائمہ کے سامنے پیش کیا اور مناسب جواب دریافت کیا ۔
مستشرقین کے آثار اور مطالعات میں تناقض
قرآن کریم کے بہت سے شبہات خصوصاتناقضات کی بحث کا سرچشمہ مستشرقین کے افکار اور آثار کا نتیجہ ہے ۔ اگر چہ قرآن تحقیقت سے بہت سے مستشرقین کا ہدف ان سے جنگ و مناظرہ تھا لیکن ان میں سے بعض مستشرقین نے مطالعہ اور عمیق تحقیق کے بعد قرآن کریم کی آیات اور تعلیمات کا اعتراف کیا ہے ۔
غیر مسلم تحقیق کرنے والے دانشوروں کا ایک گروہ جیسے : جاپانی ایزوتسوی ، اسکاٹ لینڈ کے توماس کارلایل اور عیسائی جارج زیدان، اس نتیجہ پر پہنچا کہ قرآن کریم کی تعلیمات اس قدر بلند و بالا اور الہی تعلیمات سے منطبق ہیں کہ یقینا ان کا خداوند عالم کے ساتھ ایک ارتباط پایا جاتا ہے اور خداوند عالم کی ان پر ایک خاص توجہ ہے اور اسی وجہ سے یہ جزیرة العرب کے لوگوں کی نجاست اورپوری تاریخ میں کروڑوں مسلمانوں کی سعادت کا سبب بنا ہے ، ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) پر خدا کی وحی نازل ہونے اور قرآن کریم کی آیات کے وحی ہونے کو قبول نہیں کیا ہے ،اس بنیاد پر انہوں نے قرآن کریم کو آسمانی کتاب اور اسلام کو آخری دین تسلیم نہیں کیا ہے اور اس کا اعتراف نہیں کیا ہے (۲۱) ۔ لیکن مغرب کے بعض دانشوروں جیسے فرانس کے پروفیسر ہانری کرین ، فرانس کے ڈاکٹر موریس بکائی ، برطانیہ کے جان ڈیوان پورٹ اور اٹلی کے شہید ڈاکٹر ادوار انیلی نے قرآن کریم کے سر چشمہ کو خداوند عالم کی آشکار وحی شمار کی ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جبرئیل کے ذریعہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) پر نازل ہوا ہے ۔ اس گروہ نے اپنی علمی تحقیق کے بعد جب یہ درک کرلیا کہ قرآن کریم ، وحی الہی ہے ، تو انہوں نے اپنے پہلے دین کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرلیا اوراس سلسلہ میں بہت قیمتی مقالات تحریر کئے ،ان میں سے تقریبا دو سو افراد کے نام ایک مستقل کتاب میں منتشر ہوئے ہیں (۲۲) ۔
مرحوم حسین عبداللہی خوروش نے بھی مستشرقین اور غیر مسلمان دانشوروں کا تعارف کرانے میں بہت زیادہ کوشش کی ہے جنہوں نے قرآن کریم اور اسلام کے متعلق تحقیقات کی تھیں، اور اس کی حقانیت ان کے لئے ثابت ہوگئی تھی ۔ انہوں نے تقریبا دو ہزار افراد کے نام جمع کئے اور ان کو دو جلدوں میں منتشر کئے ۔
بہرحال بعض مستشرقین نے قرآن کریم کے تناقضات اور اشکالات کے سلسلہ میں جو مطالعہ اور تحقیق کی ہے وہ آج باقی ہیں اور ان لوگوں کے نام ایک مقالہ میں منتشر ہوئے ہیں اوراس مقالہ کا نام”مبانی نظری مستشرقین در مورد تناقضات قرآن“ ہیں ۔ ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں :
۱۔ گلدزیهر. (مذاهب التفسیر الاسلامی و العقیدة و الشریعة فی الاسلام)
۲۔ یوسف درّه حدّاد. (دروس القرآنیه، القرآن و الکتاب، اطوار الدعوة القرآنیه)
۳۔ جرجس سال(مقالہ فی الاسلام کے تیسرے حصہ میں ”اسرار عن القرآن “ کے عنوان سے قرآن کریم کے تناقض کے اعتراض کو بیان کیا ہے ) ۔
۴۔ ونسینک: ”دائرة المعارف الاسلامی “ میں لفظ ”خطیہ“ اور ”رسول“کے ضمن میں ۔
۵۔ لوسیان کلیموفتش: المسلمون تحت الحکم الشّیوعی.
شبہات کے جواب میں علماء کے علمی آثار
علمائے اسلام نے بعض مستشرقین اور سود جو افراد کے مذکورہ شبہات کے جواب دینے کیلئے کتابیں اورمقالات تدوین کئے ہیں ۔ حضرت آیة اللہ محمد ہادی معرفت نے کتاب ”شبھات و ردود “ (۲۳) میں بعض دانشوروں کان ذکر کیا ہے ، سب سے اہم شخصیات جنہوں نے قرآن کریم کے شبہات اور تناقضات کا جواب دینے کی سلسلہ میں زحمت اٹھائی ہے ،ان کے نام یہ ہیں :
ابی علی محمد بن مستنیر بصری (متوفی ۲۰۶ ھ ق) یہ بہت بڑے ادیب تھے اور امام صادق (علیہ السلام) کے شاگرد تھے ،انہوں نے قرآن کریم کے شبہات کے سلسلہ میں سوروں کی ترتیب کے اعتبار سے ” الرد علی الملحدین فی تشابہ القرآن “ تالیف کی ۔
ابن قتیبہ دینوری (متوفی ۲۷۲ ھ․ق․) نے کتاب قرآن شبہات کے جواب میں ”تاویل مشکل القرآن “ تالیف کی ، اس کتاب کو محمد حسن بحری بیناباج نے ترجمہ کیا ہے اور بنیادپژوھشھای اسلامی نے مشہد مقدس میں اس کتاب کی طباعت کی ہے ۔
سید شریف رضی (متوفی : ۴۰۶ ھ․ق) نے بھی اس موضوع پر کتاب تالیف کی ہے ان کی اس قیمتی کتاب کا نام ”حقایق التاویل فی مشابہ التنزیل “ ہے ۔
قاضی عبدالجبار معتزلی (ت: ۴۱۵ ھ․ق) نے کتاب ”تنزیہ القرآن عن المطاعن“ لکھی ہے ۔
محمد الفاتح مرزوق نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب ”دفاع الاسلام ضد مطاعن التبشیر“ کے عنوان سے لکھی ہے ۔
قطب راوندی (ت: ۵۷۳ ھ․ق) نے کتاب ”الخرائج والجرائح“ میں ایک فصل شبہات کا جواب دینے سے مخصوص کی ہے ۔
ابن شہر آشوب مازندرانی (ت: ۶۶۶) نے قرآن کریم کے متعلق ۱۲۰۰ شبہات کے جواب میں ایک مجلہ لکھا ہے ۔
اسی طرح جلال الدین سیوطی نے کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ کے اڑتالیسویں باب میں تناقض کے مسئلہ کو بیان کیا ہے ۔ سید مہدی حائری قزوینی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے جس کو موسسہ انتشاراتی امیر کبیر نے طباعت کی ہے ۔
علامہ محمد باقر مجلسی نے بھی بحارالانوار میں(جلد ۸۹، صفحہ ۱۴۱ اور جلد ۹۰ ،صفحہ ۹۸ تا ۱۴۲ ) قرآنی شبہات کے بارے میں مفصل بحث کی ہے ۔
شیخ جلیل یاسینف نے بھی کتاب ”اضواء علی متشابھات القرآن “ تالیف کی ہے ۔
احمدعمران نے ”القرآن والمسیحیةفی المیزان“لکھی ہے جو کہ لبنان کے عیسائی یوسف حداد کی کتاب ”القرآن والمسیحیہ“ کا جواب ہے ۔
آیت اللہ محمد ہادی معرفت نے کتاب ”شبھات و ردود حول القرآن الکریم “ میں بہت سے قرآنی شبہات کی تحقیق کی ہے ۔ انہوں نے قرآنی تناقضات کے سلسلہ میں بہت مفصل بحث کی ہے ۔
آیت اللہ العظمی سید ابوالقاسم خویی نے بھی کتاب ”البیان فی تفسیر القرآن“ کی پہلی جلد میں قرآن کریم میں تناقض نہ ہونے کو بیان کیا ہے ۔
محمد بن ابی بکر رازی نے قرآنی شبہات کے جواب میں ۱۲۰۰ سے زیادہ سوالوں کا جواب دیا ہے ۔
استاد خلیل یاسین نے ایک کتاب ”اضواء علی متشابھات القرآن“ نامی کتاب لکھی ہے جس میں ۱۶۰۰ سوالوں کا جواب دیا ہے ۔
آیت اللہ جعفر سبحانی نے آیات مشکلة کے متعلق بہترین کتاب تالیف کی ہے ۔
بہت سے مفسرین جیسے آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ طباطبائی نے سورہ نساء کی ۸۲ ویں آیت کے ذیل میں قرآن کریم میں تناقض اور اختلاف نہ ہونے کو بیان کیا ہے ۔
سید علی رضا صدر حسینی نے ایک کتاب ”نقدی بر کتاب تولدی دیگر“ کے عنوان سے شبہات کی تحقیق میں لکھی ہے ۔ الہی ادیان اور قرآن کے متعلق جو کہ کتاب ”تولدی دیگر“ میں بیان ہوئے ہیں ،ذکر کئے ہیں ۔
قرآن کریم میں تناقض پیش کرنے کا ہدف
ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آئین اسلام تمام ادیان اور قوانین سے بلند وبالا ہے ۔ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) بھی خاتم الانبیاء ہیں اور آسمانی آخری کتاب کو معجزہ الہی کے عنوان سے ہدایت بشری کے لئے لائے ہیں ۔ تمام ادیان پر دین اسلام کی برتری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے ۔ ایسی کتاب جس کی تعلیمات میں کسی بھی شخص یہاں تک کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے بھی اپناسلیقہ نہیں اپنایا اور یہی بات سبب بنی ہے کہ یہ آسمانی کتاب اختلاف، تناقض اور کجی سے محفوظ رہی ہے ۔
اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ سود جو افراد اور جو لوگ قرآن اور اسلام کی برتری کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لئے جو مکر و حیلہ استعمال کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے اعجاز میں شک و شبہات ایجاد کرنا ہے ۔
تناقض کا وہم کرنے کے علل و اسباب
جو چیزیں مسلمات میں شمار ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں ہر طرح کا اختلاف وتناقض صرف ایک توہم اور خیال ہے ۔ اگر چہ پہلی نظر میں جس میںظاہری بینی پائی جاتی ہے ، بعض آیات کے ظواہر سے ایک دوسرے میں اختلاف نظر آتا ہے لیکن اس طرح کے اختلاف جن کا سرچشمہ ”عام و خاص“،”ناسخ ومنسوخ“ اور آیات ”محکم و متشابہ“ ہیں ، قرآن کی سلامتی میں کوئی خدشہ وارد نہیں کرتے ۔ لہذا اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ قرآن کریم میں تناقض اور اختلاف کے وہم کا ایک سبب لوگوں کا قرآن کریم کے علوم اور مفاہیم سے آشنا نہ ہونا ہے ۔ البتہ دوسرے علل و اسباب بھی موجود ہیں جن کی طرف قرآن کریم کے محققین نے اشارہ کیا ہے ۔
آیت اللہ محمد ہادی معرفت اورجلال الدین سیوطی نے زرکشی کی کتاب ”البرھان فی علوم القرآن “ سے نقل کرتے ہوئے تناقض کے وہم و خیال کے پانچ علل واسباب بیان کئے ہیں ۔ محقق ارجمند حسین طوسی نے بھی ”قرآن کریم میں تناقض کے شبہات کی تحقیق “ کے عنوان سے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے اور دوسرے تین علل و اسباب بیان کئے ہیں ۔
اس بناء پر قرآن کریم کی آیات میں اختلاف کے وہم و گمان کے اسباب ، یادوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ قرآن کریم میں تناقض اور اختلاف کے وہم و گمان کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں :
۱۔ ایک موضوع کے مختلف حالات اور تبدیلیوں کو بیان کرنا ، مثلا وہ آیتیں جو انسان کی خلقت کو بیان کرتی ہیں ۔
۲۔ ایک موضوع کی ایک یا دو آیتوں میں اختلاف ،مثلا آیات سوال اور قیامت میں سوال کا نہ ہونا ۔
۳۔ فعل کے اعتبار سے دو آیتوں میں اختلاف : مثلا جو کچھ آیت ”فلم تقتلوھم و لکن ا للہ قتلھم و ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی“ میں آیا ہے ۔
۴۔ حقیقت و مجاز میں اختلاف : مثلا جیسا کہ آیت ”و تری الناس سکاری وما ھم یسکاری“ میں ذکر ہوا ہے ۔
۵۔ دو اعتبار کی وجہ سے اختلاف (۲۴) ۔
۶ ۔ متشابہات اور محکمات کے حکیمانہ قانون کا علم نہ ہونا ۔
۷ ۔ موانع، حجاب اور آفات شناخت ۔
۸ ۔ علم منطق کے قوانین کا علم نہ ہونا ۔
بعض آیات میں تناقض کی تحقیق
اس حصہ میں ان آیات کی تحقیق کرتے ہیں جو ظاہر میں ایک دوسرے سے متناقض ہیں اور یہی بات سبب ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے ان آیات کے درمیان تناقض کا وہم و گمان کیا ۔ اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ یہ اشکالات کسی بھی صورت میں جدید اشکال نہیں ہیں اور یہ وہی اعتراضات ہیں جو ائمہ (علیہم السلام) خصوصا امیرالمومنین (علیہ السلام) کے سامنے بہت سے لوگوں نے بیان کئے تھے ، اس زمانہ کے اعتراض کرنے والے ان اشکالات میں ایک اشکال کا بھی اضافہ نہیں کرسکے اور انہیں سوالوں کو بار بار تکرار کرتے رہتے ہیں ۔ ان اشکالات کی ائمہ (علیہم السلام) اور علمائے اسلام نے تحقیق کرنے کے بعد جوابات دئیے ہیں ۔ ہم یہاں پر ان میں سے مہم ترین اشکالات کی تحقیق کریں گے:
۱۔ شبھہ : صرف خدا وندعالم خالق ہے یا ․․․؟
قرآن کریم کی دو آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم ”احسن الخالقین“ ہے ،یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دوسرے خلق کرنے والے بھی موجود ہیں جن میں خداوندعالم بہترین اور برترین ہے ۔ جب کہ سورہ زمر کی ۶۲ ویں آیت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم تمام چیزوں کا خلق کرنے والا ہے ”اللہ خالق کل شیء “ ۔ کیا ان آیات کے درمیان تناقض نہیں ہے ؟
جواب : سب سے پہلے ضروری ہے کہ لفظ ”خلق“ کے معنی اوراستعمال سے آشنائی حاصل کریں ۔ ”خلق“ ، ”تقدیر اور اندازہ گیری“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور دو طریقوں سے اس کا استعمال ہوتا ہے :
۱۔ ایسی چیز کو ایجاد کرنا جس کے اجزاء اس کے وجود سے قبل موجودتھے ، مثلا : ایک ہنری چیز کو خلق کرنا اور ہر وہ چیز جسے انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور اس کے قطعات واجزاء کو اپنی طبیعت کے لحاظ سے آمادہ کرتا ہے ۔ اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ انسان کسی چیز کو بنانے اور خلق کرنے میں اجزاء کا محتاج ہے اور وہ اجزاء اورقطعات کو مستقیم یا غیر مستقیم اپنی طبیعت کے لحاظ سے حاصل کرتا ہے اوراس کے بغیر وہ کسی بھی چیز کو خلق نہیں کرسکتا ، دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ انسان اس کام میں خداوند عالم اور اس کی مخلوقات سے بے نیاز نہیں ہے ۔
قرآن کریم میں خلق کے اس معنی کی نسبت انسان کی طرف دی گئی ہے ۔سورہ آل عمران میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت عیسی (علیہ السلام) نے قوم بنی اسرائیل سے کہا : ” اٴَنِّی اٴَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ فَاٴَنْفُخُ فیہِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللَّہِ “(۲۶) ۔ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندہ کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کردوں گا تو وہ حکمِ خدا سے پرندہ بن جائے گا ۔
سورہ مائدہ میں بھی خداوند عالم نے اسی تعبیر میں واقعہ کونقل کیا ہے اور کہا ہے : ” وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنی فَتَنْفُخُ فیہا فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذْنی“ (۲۷)۔ جس وقت تم میرے حکم سے مٹی کے ذریعہ پرندہ کی شکل بناؤ )۔
ان آیات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسی(علیہ السلام) نے مٹی سے جو کہ خداوند عالم کی مخلوق کا جزء ہے،خداوند عالم کے حکم سے کبوتر بنایا ۔
۲۔ مطلق طور پر ایجاد کرنا یعنی کسی چیز کو اس طرح ایجاد کرنا جو اس سے پہلے موجود نہ ہو ۔ اس طرح کی خلقت ، خداوند عالم سے مخصوص ہے ، کوئی بھی شخص اس طرح کی خلقت کوایجاد کرنے میں خداوند عالم کے ساتھ شریک نہیں ہوسکتا ،اسی وجہ سے خداوند عالم نے سورہ حج میں مشرکین سے کہا ہے : ” إِنَّ الَّذینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّہِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً “ (۲۸)۔یہ لوگ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر آواز دیتے ہو یہ سب مل بھی جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کرسکتے ہیں ۔
یہ آیت ایک طرف تو شرک کی مذمت کرتی ہے اوردوسری طرف خلقت استقلالی کو خداوند عالم کی شناخت کے لئے نشانی بتاتی ہے کیونکہ صرف خداوند عالم ہی اس طرح خلق کرتا ہے ۔
مندرجہ ذیل آیات میں خلق سے مراد وہی خلقت ہے جو خداوند عالم سے مختص ہے :” لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ “ (۲۹). ” قُلِ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ “(۳۰)”ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ خالِقُ کُلِّ شَیْء “ (۳۱) ۔
اس بناء پر گذشتہ مطالب کو مدنظر رکھتے ہوئے خداوند عالم کے علاوہ بھی دوسرے خالق موجود ہیں لیکن وہ محتاج اور غیر مستقل ہیں اور فطری سی بات ہے کہ خداوند عالم چونکہ وہ خود مستقل ہے لہذا ان سب سے برتر ہے اور حقیقی خالق وہی ہے پس یہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ خداوند عالم ” احسن الخالقین“ہے ، صحیح ہے ۔
۲۔ اشکال : خداوند عالم کے لئے فرزند ہونے کا امکان؟
سورہ زمر کی چوتھی آیت میں بیان ہوا ہے : ”لَوْ اٴَرادَ اللَّہُ اٴَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً لاَصْطَفی مِمَّا یَخْلُقُ ما یَشاء ُ “ ۔اور وہ اگر چاہتا کہ اپنا فرزند بنائے تو اپنی مخلوقات میں جسے چاہتا اس کا انتخاب کرلیتا ۔ لیکن اس کے باوجود سورہ انعام کی ۱۰۱ ویں آیت میں فرماتا ہے : ”ِ اٴَنَّی یَکُونُ لَہُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَکُنْ لَہُ صاحِبَةٌ“ ۔ اس کے اولاد کس طرح ہوسکتی ہے اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے ۔کس طرح قرآن ایک آیت میں خداوند عالم کے لئے فرزند کو ممکن اور دوسری آیت میں غیر ممکن بیان کرتا ہے ؟
جواب : حقیقت میں سورہ زمر کی چوتھی آیت مشرکوں کے کلام کا جواب ہے جس میں وہ فرشتوں کو خداوند عالم کی لڑکیاں باتے تھے ۔ پہلا کہتا ہے : ”لَوْ اٴَرادَ اللَّہُ اٴَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً لاَصْطَفی مِمَّا یَخْلُقُ ما یَشاء ُ “ ۔اور وہ اگر چاہتا کہ اپنا فرزند بنائے تو اپنی مخلوقات میں جسے چاہتا اس کا انتخاب کرلیتا ۔اس کے بعد کہتا ہے : ”سُبْحانَہُ ہُوَ اللَّہُ الْواحِدُ الْقَہَّارُ“۔ ہ پاک و بے نیاز ہے کہ اس کے فرزند ہو اور وہی خدائے یکتا اور قہار ہے ۔
پہلے جملہ کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف تفسریں بیان کی ہیں :
بعض علماء نے کہا ہے : اس سے مراد یہ ہے : اگر خداوند عالم چاہتا کہ اپنے لئے فرزند اختیار کرے تولڑکیوں کا انتخاب کیوں کرتا کیونکہ تمہارے وہم وگمان کی بناء پرلڑکیاں بہت ہی کم اہمیت رکھتی ہیں؟
لڑکوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ حقیقت میں یہ طرف مقابل کی ذہنیت کے مطابق ایک طرح کا استدلال ہے تاکہ وہ اپنے کلام کی اہمیت کو سمجھ لے ۔
دوسرے بعض علماء نے کہا ہے : مراد یہ ہے : اگر خدا چاہتا کہ اس کے اولاد ہو تو وہ فرشتوں سے بہتر اور برتر مخلوق کو خلق کرتا ۔
لیکن اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ لڑکیوں کی اہمیت خداوند عالم کے نزدیک لڑکوں سے کم نہیں ہے ،فرشتہ اور حضرت عیسی (علیہ السلام) جو کہ منحرف لوگوں کے بقول خدا کے فرزند ہیں ، بہترین اور لایق مخلوق ہیں ۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک تفسیر بھی صحیح نہیں ہے ۔
بہتر یہ ہے کہ کہا جائے : ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرزند ”مدد“ یا ”روحی انس و محبت“ کے لئے ضروری ہے ، بالفرض محال اگر خداوند عالم کو ان چیزوں کی ضرورت بھی ہو جب بھی فرزند کا ہونا لازمی نہیں ہے ، بلکہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کاانتخاب کرلیتا جو اس ہدف کو پورا کردیتا لہذا فرزند کا انتخاب کیوں کرتا؟ لیکن چونکہ وہ واحد، یک و تنہا،ہر چیز پر غالب، ازلی اور ابدی ہے لہذا اس کو نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ اس میں کسی خوف و وحشت کا تصور کیا جاسکتا ہے جس کے ذریعہ وہ کسی چیز سے انس کرے تاکہ وہ خوف ختم ہوجائے اورنہ اس کو اپنی نسل کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس بناء پر وہ اولاد رکھنے سے پاک و منزہ ہے چاہے وہ حقیقی اولاد ہو یا انتخابی اولاد ہو (۳۲) ۔
خداوندعالم نے بارہا ان لوگوں کے عقیدہ اور کلام کو رد کیا ہے جو کہتے ہیں : ” اتخذاللہ ولدا“۔ خداوندعالم نے اپنے لئے فرزند انتخاب کیا ہے ۔ اوراس کے جواب میں کہا ہے : ”سبحانہ “ : وہ ان ناجائز نسبتوں سے پاک و منزہ ہے ۔ جیسا کہ انہی تعبیر کے ساتھ سورہ زمر کی چوتھی آیت میں اس وہم و گمان کورد کیا ہے ۔
نتیجہ یہ ہوا کہ اس آیت ، سورہ انعام کی ۱۰۱ ویں آیت اوردوسری آیتوں میں جو کہ خداوند عالم کے فرزند ہونے کی نفی کرتی ہیں ،کوئی منافات نہیں ہے ۔
۳۔ اشکال : خداوند عالم کسی جگہ پر ہے یا نہیں؟
کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم کسی جگہ پر نہیں ہے لیکن سورہ ”ق“ کی ۱۶ ویں آیت میں کہا گیا کہ شہ رگ سے بھی زیادہ انسان سے نزدیک ہے ۔ سورہ حدید کی چوتھی آیت میں ذکر ہوا ہے کہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور سورہ ہود کی ساتویں آیت کے مطابق پانی پر رواں دواں ہے ! بہر حال خداوند عالم کس جگہ پر ہے یا نہیں؟اگر ہے توکہاں ہے ؟
جواب : جن آیات میں شبھہ ذکر کیا گیا ہے یہ متشابہ آیات ہیں بعض آیات میں خداوند عالم کا انسان سے نزدیک ہونا اور عرش و کرسی پر ہونا ذکر ہوا ہے ۔ یہی بات سبب بنی کہ بہت سے لوگ اشتباہ میں پڑ جائیں ۔ ان آیات کے صحیح معنی سمجھنے کےلئے ان کی تحقیق کرتے ہیں:
۱۔ خداوند عالم نے سورہ ”ق“ میں فرمایا ہے : ہم اس (انسان) سے اس کے دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں ” نحن اقرب الیہ من حبل الورید“ ۔ بعض علماء نے ”حبل الورید“ کو گردن کی رگ بیان کیا ہے ، لیکن آیت اللہ مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں او رعلامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اس کو قلب کی رگ سے تعبیر کیا ہے ۔ البتہ ان مذکورہ معانی کے ذریعہ آیت کا مفہوم واضح ہے ۔ اس آیت میں کنایہ کے طور پر ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور وہ سب سے پہلے ہم سے آگاہ ہے جس طرح سے نزدیک ترین دوست ایک دوسرے کے حال و احوال سے آگاہ ہوتے ہیں ۔
آیت کے بعد والے حصہ سے یہ معنی اور زیادہ واضح ہوجاتے ہیں ۔ قرآن کریم پہلے انسان کے اعمال کے متعلق علم الہی کو بیان کرتا ہے اس کے بعد ان دو فرشتوں کا تذکرہ کرتا ہے جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں اور کہتا ہے : إِذْ یَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّیانِ عَنِ الْیَمِینِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِیدٌ“ ۔ یاد کرو ، اس وقت کو جس وقت انسان کے داہنے اور بائیں دو فرشتے اس کی مراقبت کرتے ہیں اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں اوراس کے اعمال کولکھتے ہیں ۔
اس بنیاد پر اس آیت سے مراد انسانوں کے اعمال سے متعلق علم الہی کا مسئلہ ہے جس کو اس کنایہ اور لکھنے والے دو فرشتوں سے اشارہ کیا ہے ۔
۲۔ سورہ حدید اور سورہ ھود میں ”عرش الہی“ کے متعلق بیان ہوا ہے : ان سوروں میں بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم عرش پر بیٹھا ہوا ہے ”ثم استوی علی العرش “ اور اس کا عرش پانی پر رکھا ہوا ہے ”کان عرشہ علی الماء “ ۔
ان آیات میں جو کہ متشابہ آیات ہیں ، کنایہ استعمال ہوا ہے اور ”عرش“ اس کی قدرت وحکمت کی طرف اشارہ ہے ۔
لغت میں عرش کے معنی چھت یا بلند ستونوں کا تخت ہے ، بادشاہوں اور سلاطین کے تخت کو عرش کہا جاتا ہے جو سلطان کے نفوذ اور قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب بھی کسی بادشاہ کی قدرت اور سلطنت ختم ہوجاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے شکست کھالی : ”ثل عرشہ ثل عرشہ ثُل عرشہ ثُل عرشہ“۔ یعنی اس کو بادشاہت کے تخت سے نیچے اتار دیا ۔
اس بناء پر ان آیات کے معنی واضح ہوجاتے ہیں جن میں عرش استعمال ہوا ہے ۔
”عرشہ علی الماء“ سے مراد کیا ہے ؟ کہا جاتا ہے : اس کے ذریعہ دنیا کی ابتداء کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ، کیونکہ کلمہ ”ماء“ کے معنی ”پانی“ کے ہیں لیکن کبھی کبھی ہر سیال چیز کو ”پانی“ کہا جاتا ہے ، جیسے سیال دھات وغیرہ ۔ اس بناء پر دنیا اپنی ابتدائی خلقت میں پگھلی ہوئی دھات کی شکل میں تھا ۔ پھر اس پانی کے ذخیرہ میں شدید حرکت اور عظیم موجیں آنے لگیں، اور اس کی سطح کے کچھ حصے پے در پے اس سے باہر نکلنے لگے ، یہ اتصال ، جدائی میں تبدیل ہوگئی اور کواکب، سیارے اور دوسرے شمسی منظومے ایک بعد ایک تشکیل پانے لگے ، اس بناء پر یہ دنیا اور خدا کی قدرت کے تخت کے پایے اس عظیم پانی کے مادے پر رکھے گئے (۳۳) ۔
۳۔ دوسری بعض آیات میں ”کرسی الہی “ کے متعلق بیان ہوا ہے ، آیة الکرسی میں کہا گیا ہے کہ اس کے تخت نے آسمانوں اور زمین کو اپنے قبضہ قدرت میں لے لیا : ”وسع کرسیہ السموات والارض “ ۔
اور چونکہ چھوٹے تخت کو کرسی کہتے ہیں اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے تصور کیا کہ خداوند عالم کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے ۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرسی دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے ، اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ استاد اور معلم درس دیتے اور سیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہیں ،اس لئے کبھی کبھی کرسی کے ذریعہ علم کو مراد لیتے ہیں اور چونکہ کرسی انسان کی قدرت کے ماتحت ہے اس لئے کبھی کسی علاقہ پر حکومت، قدرت اور فرمانروائی کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے ۔
اس بناء پر آیت ”وسع کرسیہ السموات والارض “ میں کرسی سے مراد یا خداوندعالم کی حکومت اور قدرت یعنی زمین و آسمان ہیں یا علم الہی کے نافذ ہونے کی جگہ یعنی تمام آسمان اور زمین ہیں ۔
متعدد روایات میں بھی اسی معنی پر تکیہ کیا گیا ہے ، منجملہ ”حفص بن غیاث“ نے نقل کیا ہے : میں نے امام صادق (علیہ السلام) سے پوچھا : ”وسع کرسیہ السموات والارض“ سے کیا مراد ہے ؟ فرمایا : اس کا علم مراد ہے ۔ (۳۴) ۔
۴۔ شبھہ : حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے یا دریا کے ساحل پر؟
سورہ صافات کی ۱۴۵ ویں آیت میں فرمایا ہے : ہم نے ان کو جس وقت وہ مریض تھے ، دریا کے کنارے ڈال دیا ۔ لیکن سورہ قلم کی ۴۹ ویں آیت میں فرمایا ہے : مچھلی کے پیٹ سے باہر ڈال دیا ، کیا یہ دونوں آیتیں قرآن کریم کی تناقض گوئی پر دلالت کرتی ہیں ۔
جواب : بعض روایات کے مطابق حضرت یونس (علیہ السلام) نے چالیس سال تک اپنی قوم کے درمیان تبلیغ کی لیکن آخر کار اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس ہوگئے اورانہوں نے ان کے لئے بددعا کی اور پھر کشتی پر سوار ہوگئے تاکہ وہاں سے دور چلے جائیں، دریا میں ایک بہت بڑی مچھلی نے کشتی کے راستہ کو روک کرمنہ کھولا گویا وہ کھانا مانگ رہی تھی ،کشتی میں سوار لوگوں نے قرعہ ڈالا تاکہ کسی کو اس مچھلی کا کھانے کے عنوان سے اس کے منہ میں ڈال دیا جائے ، قرعہ حضرت یونس (علیہ السلام) کے نام نکلا !
ایک روایت کے مطابق تین مرتبہ قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار حضرت یونس (علیہ السلام) ہی کا نام نکلا ،مجبورا حضرت یونس کو اٹھا کر مچھلی کے منہ میں ڈال دیا !
قرآن کریم نے ایک مختصر جملہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے : یونس نے ان کے ساتھ قرعہ ڈالا اور مغلوب ہوگئے ” فساھم فکان من المدحضین“ ۔
واقعہ کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے : عظیم مچھلی نے ان کو نگل لیا جب کہ وہ خود اپنے نفس کی ملامت کررہے تھے ۔
حضرت یونس (علیہ السلام) کو ملامت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ترک اولی انجام دیا تھا ، بہتر یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو تنہا نہ چھوڑتے ۔ آخر کار انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تسبیح اور توبہ کے ذریعہ مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل کی ۔ سورہ انبیاء کی ۸۸ویں آیت میں ذکر ہوا ہے : ”فَاسْتَجَبْنا لَہُ وَ نَجَّیْناہُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنین“ ۔ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کرلیا اور انہیں غم سے نجات دلادی ۔
لیکن خداوند عالم فرماتا ہے : اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے ․․․․ ”فلولا انہ کان من المسبحین“ ۔ یقینا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ! ”للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون “ ۔
اب اصل شبھہ کی طرف واپس آتے ہیں ۔ خداوندعالم سورہ صافات کی ۴۵ ویں آیت میں فرماتا ہے : پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جب کہ وہ مریض بھی ہوگئے تھے ”فَنَبَذْناہُ بِالْعَراء ِ وَ ہُوَ سَقیم“ ۔ یہ آیت اس چیز کے ساتھ منافات نہیں رکھتی جو اوپر بیان کی ہے ۔
سورہ قلم کی ۴۹ ویں آیت میں خداوندعالم نے فرمایا ہے : ”لَوْ لا اٴَنْ تَدارَکَہُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّہِ لَنُبِذَ بِالْعَراء ِ وَ ہُوَ مَذْمُومٌ“ ۔ اگر انہیں نعمت پروردگار نے سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں چٹیل میدان میں برے حالوں میں چھوڑ دیا جاتا ۔
یہ آیت بھی مذکورہ آیات سے کوئی منافات نہیں رکھتی کیونکہ اس آیت میں بھی وضاحت ہوئی ہے کہ حضرت یونس (علیہ السلام) نے نجات حاصل کی ۔ لیکن اگر خداوند عالم کی رحمت نہ ہوتی تو نجات حاصل کرتے لیکن ان کا ترک اولی معاف نہ ہوتا اور وہ مستحق کے سرزنش ہوتے ، لیکن ایسا نہیں تھا کہ نجات حاصل نہ کرتے ۔
اس بناء پر یہ آیتیں ایک دوسرے کے تناقض نہیں رکھتیں اور اشکال کرنے والوں نے سورہ قلم کی ۴۹ ویں آیت میں بہت بڑی غلطی کی ہے ۔
۵۔ شبھہ : آسمان وزمین کی خلقت ۶ دن میں ہوئی ہے یا ۸ دن میں ہوئی ہے ؟
خداوند عالم نے سورہ فصلت کی نو سے بارہویں آیتوں میں کہا ہے : زمین و آسمان آٹھ دنوں میں خلق ہوا ہے ،لیکن سورہ سجدہ کی چوتھی آیت اور قرآن کریم کی دوسری ساتھ آیتوں میں کہا ہے : ”فی ستة ایام“ یعنی چھے روز میں زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے ۔ ان آیتوں کو کس طرح جمع کیا جاسکتا ہے ؟
جواب : اس مسئلہ کو واضح کرنے کیلئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان آیات کے معنی میں غور و فکر کریں ۔
خداوند عالم نے سورہ فصلت میں زمین و آسمان کی خلقت کے مراحل کو بیان کرتے ہوئے اس طرح فرمایا ہے : ” قُلْ اٴَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذی خَلَقَ الْاٴَرْضَ فی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَہُ اٴَنْداداً ذلِکَ رَبُّ الْعالَمینَ ، وَ جَعَلَ فیہا رَواسِیَ مِنْ فَوْقِہا وَ بارَکَ فیہا وَ قَدَّرَ فیہا اٴَقْواتَہا فی اٴَرْبَعَةِ اٴَیَّامٍ سَواء ً لِلسَّائِلین… فَقَضاہُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فی یَوْمَیْن“ ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ساری زمین کو دو دن میں پیدا کردیا ہے اور اس کا مثل قرار دیتے ہوئے جب کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے اور اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ قرار دے دیئے ہیںاور برکت رکھ دی ہے اور چار دن کے اندر تمام سامان معیشت کو مقرر کردیا ہے جو تمام طلبگاروں کے لئے مساوی حیثیت رکھتا ہے… پھر ان آسمانوں کو دو دن کے اندر سات آسمان بنادیئے ۔
خداوند عالم نے مذکورہ آیات میں تین زمانوں کی طرف اشارہ کیا ہے :
۱۔ زمین کی خلقت کا پہلا مرحلہ (دو دن : فی یومین) ۔
۲۔ زمین کی خلقت کا پہلا مرحلہ ، زمین کو پھیلانے کے ساتھ (چار دن، دو دن زمین کی خلقت کے اور دو دن اس کو پھیلان کے لئے: فی اربعة ایام) ۔
۳۔ آسمان کی خلقت کا مرحلہ (دو دن : فی یومین) ۔
اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ”زمین کی خلقت کا پہلا مرحلہ “ ایک جدا اور ایک مرتبہ ”زمین کو پھیلانے کے مرحلہ“ کے ساتھ شمار ہوا ہے لہذا مراد یہ ہے : زمین کی خلقت کا پہلا مرحلہ دو روز میں انجام پایا اوراس کے بعد دو دن میں زمین کو پھیلایا گیا لہذا دونوں کو ملانے کے بعد پوری زمین کی خلقت چار روز ہوتی ہے ۔ یہ زمانہ اور آسمان کو خلق کرنے کا زمانہ جو کہ دو روز ہے دونوں کو ملا کر چھے دن ہوتے ہیں ۔
اس بناء پر اس آیت اور جن آیات میں آسمان و زمین کی خلقت کے زمانہ کو چھے دن بیان کیا گیا ہے ،ان میں کوئی تضاد نہیں ہے ۔
اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ علامہ طباطبائی اور حضرت آیت اللہ محمد ہادی معرفت کے بیان کرنے کے مطابق ان آیات میں ”یوم“ کے معنی دورہ اور مرحلہ کے ہیں ۔
۶ ۔ شبھہ : پہلے زمین خلق ہوئی یا آسمان خلق ہوا ؟
سورہ بقرہ کی ۲۹ ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ زمین کی خلقت ، آسمان کی خلقت سے پہلے ہوئی ہے لیکن سورہ نازعات (آیت ۲۷ سے ۳۰) میں بیان ہوا ہے کہ آسمان کی خلقت ، زمین سے پہلے ہوئی ہے ، کیا ان آیات میں تناقض نہیں پایا جاتا ؟
جواب : قرآن کریم نے آسمان وزمین کی خلقت کے سلسلہ میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے : ”ہُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْاٴَرْضِ جَمیعاً ثُمَّ اسْتَوی إِلَی السَّماء “ ۔ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لئے پیدا کیا ہے،اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا ۔
اس آیت میں زمین کی خلقت کو آسمان سے پہلے بیان کیا ہے ۔
لیکن بعض علماء کے دعوی کے مطابق سورہ نازعات میں اس کے برعکس ہے ۔ سورہ نازعات کی ۲۷ ویں آیت میں پہلے آسمان کی خلقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے : ”السَّماء ُ بَناہا“ ۔ اور اس کے بعد فرمایا : ”وَ الْاٴَرْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحاہا“ ۔ اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا ہے ۔
سورہ نازعات میں غوروفکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی خلقت کے بعد جو کچھ بیان ہوا ہے وہ زمین کو پھیلانا (دحوالارض) بیان ہوا ہے ، زمین کی خلقت بیان نہیںہوئی ہے ۔ اس بناء پر زمین کی خلقت آسمان کی خلقت سے پہلے ہے اور زمین کو آسمان کی خلقت کے بعد پھیلایا گیا ہے ۔ سورہ فصلت کی نویں اور دسویں آیات بھی زمین کی خلقت اور اسے پھیلانے کو دو الگ الگ مرحلوں میں بیان کیا گیا ہے ۔
اس بناء پر ان آیات میں کسی طرح کا کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے ۔
۷ ۔ شبھہ : انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی، یا پانی سے یا خون سے یا ․․․؟
قرآن کریم نے انسان کی پہلی خلقت کومختلف صورتوں میں بیان کی ہے کبھی کہتا ہے انسان مٹی سے پیداہوا ہے اورکبھی کہتا ہے خون سے یاپانی کے قطرہ وغیرہ سے بنا ہے ․․․! بہرحال انسان کس چیز سے خلق ہوا ہے ؟ کیا ان آیات کے درمیان اختلاف و تناقض نہیں ہے ؟
جواب : بدرالدین زرکشی نے قرآن کریم کی آیات میں تناقض اور اختلاف کا وہم و گمان کے متعلق فرمایا :ان میں سے جگہ وہ ہے جہاں پر ایک موضوع کی مختلف حالتوں اور اس کے رشد کے مراحل کو بیان کیا ہے ، مثال کے طور پر قرآن کریم نے انسان کے رشد کے مختلف مراحل کو مختلف تعبیروں سے یاد کیا ہے ۔ ان میں سے ہر ایک تعبیر ”خلقہ من تراب“(۳۵)۔ ”من حما مسنون“ (۳۶) ۔ ”من صلصال کالفخار“ (۳۷) انسان کی خلقت کے مرحلوں کی طرف اشارہ کرتی ہے ۔ اس بناء پر ان آیات میں کوئی تناقض اور اختلاف نہیں ہے ۔
۸ ۔ شبھہ : حضرت موسی (علیہ السلام) کا سانپ چھوٹا سانپ بنا تھا یا بہت بڑا اژدھا؟
قرآن کریم میں حضرت موسی (علیہ السلام) کے عصا کے بارے میں مختلف تعبیریں بیان ہوئی ہیں ۔ ایک جگہ پر اس کو اژدھا بیان کیا ہے اور کہا ہے : ”فاذا ھی ثعبان مبین“ ۔ اور دوسری آیت میں کہا ہے کہ ایک چھوٹے سے سانپ کی شکل میں بن گیا تھا ” کانھا جآن“۔ کیا ان دونوں آیتوں میں تناقض نہیں ہے ؟
جواب : ان دونوں آیتوں میں کسی طرح کا کوئی تناقض نہیں ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک آیت الگ واقعہ کو بیان کررہی ہے یعنی حضرت موسی (علیہ السلام) کا عصا ایک جگہ ”ثعبان“ اژدھا میں تبدیل ہوگیا تھا اوردوسری جگہ ”جآن“چھوٹا سانپ بن گیا تھا ۔ پہلی آیت اس وقت سے مربوط ہے جب حضرت موسی (علیہ السلام) نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے معجزہ پیش کیا تھا ، لیکن بعد والی آیت آپ کی بعثت کی ابتداء کے واقعہ سے مربو ط ہے ۔
۹۔ شبھہ : قیامت میں انسان سے سوال کیا جائے گا یا سوال نہیں کیا جائے گا؟
سورہ صافات (۳۹) اور سورہ اعراف (۴۰) میں قیامت کے روز سوال کرنے کے متعلق خبر دی گئی ہے لیکن سورہ رحمن میں کہا گیا ہے : ”فَیَوْمَئِذٍ لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِہِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ“ ۔ پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا ۔ اس طرح کی آیات کو کس طرح سے ایک جگہ جمع کیا جاسکتا ہے ؟
جواب : حضرت آیت اللہ محمد ہادی معرفت نے حلیمی سے نقل کرتے ہوئے اس اشکال کا جواب دیا ہے : پہلی آیت سے مراد یہ ہے کہ قیامت میں توحید سے متعلق سوال کیا جائے گا اوردوسری آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کی تصدیق کے بارے میں سوال کیا جائے گا لیکن تیسری آیت میں سوال کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت کے اقرار کی وجہ سے قیامت کے روز فروع دین اور احکام کے متعلق سوال نہیں ہوگا(۴۱) ۔
آیت اللہ محمد ہادی معرفت نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے قیامت کے مراحل کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہر مرحلہ میں بندوں کی حالت کو بیان کیا ہے (۴۲) ۔ بعض مراحل میں سوال وجواب نہیںہوگا اور بعض مراحل میں یا بندوں سے سوال کیا جائے گا یا بندے خود آپس میں باتیںکریں گے ۔ مثال کے طور پر قیامت کے پہلے مرحلہ میں جو کہ بہت زیادہ سخت مرحلہ ہے ،سب بے ہوش ہوجائیں گے ۔ قرآن کریم سورہ حج کی دوسری آیت میں کہتا ہے : ”وَ تَرَی النَّاسَ سُکاری وَ ما ہُمْ بِسُکاری“ ۔ اور لوگ نشہ کی حالت میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ بدمست نہیں ہوں گے(۴۳)۔اس مرحلہ میں انسان تمام چیزوں سے بے خبر ہیں اور دوستوں کو ایک دوسرے سے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے ۔
خداوند عالم قیامت کے دوسرے مرحلہ میں مجرموں کی حالت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ ان کو آواز دی جائے گی : ”‘وَ قِفُوہُمْ إِنَّہُمْ مَسْؤُلُون‘ ۔ اور ذرا ان کو ٹہراؤ کہ ابھی ان سے کچھ سوال کیا جائے گا ۔سورہ مدثر کی ۳۹ سے ۴۸ ویں آیت میں فرمایا ہے : اصحاب یمین جنتوں میں رہ کر آپس میں مجرمین کے بارے میںسوال کررہے ہوں گے ”ما سَلَکَکُمْ فی سَقَر“ ۔ آخر تمہیں کس چیز نے جہنمّ میں پہنچادیا ہے(۴۵)۔بعض انسانوں سے بہت زیادہ سوال کیا جائے گا ۔
تفسیر نمونہ میں بھی اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اس روز اور دوسرے مرحلہ میں انسان آپس میں جنگ و جدال اوردفاع کریں گے ،خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت کے کچھ شرایط ہیں اور ہر وقت دوسرے وقت سے زیادہ خوفناک ہے ۔
اس لئے سوال نہیں کریں گے کہ اس روز تمام چیزیں آشکار ہیں اور تمام انسانوں کے چہروںپر پڑھی جائیں گی ۔ ممکن ہے یہ تصور کیاجائے کہ یہ بات ان آیات کے ساتھ تضاد رکھتی ہیں جن میں قیامت کے روز بندوں سے سوال کرنے کی تصریح اورتاکید کی گئی ہے ، جیسے سورہ صافات کی ۲۴ ویں آیت اور سورہ ہجر کی ۹۲ و ۹۳ ویں آیتیں : ”فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّہُمْ اٴَجْمَعینَ ، عَمَّا کانُوا یَعْمَلُون“ ۔ لہذا آپ کے پروردگار کی قسم کہ ہم ان سے اس بارے میں ضرور سوال کریں گے ، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ۔لیکن ایک نکتہ کی طرف توجہ کرنے سے یہ مشکل حل ہوجاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت ایک بہت لمبا دن ہے اور انسان کو متعدد گذرگاہوں اورمواقف سے گزرنا ہوگا اور ہر مقام پر کچھ دیر کھڑا ہوگا ، بعض روایات کے مطابق یہ موقف پچاس ہیں ۔ ان میں سے بعض مواقف پر بالکل کوئی سوال نہیں ہوگاجیسا کہ سورہ رحمن کی اس آیت ”فَیَوْمَئِذٍ لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِہِ إِنْسٌ وَ لا جَان“ ۔ کے بعد فرمایا ہے : ”یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسیماہُم“ (مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا)۔ اور بعض مواقف پر ان کے منہ پر مہر لگادی جائے گی اور ان کے اعضائے بدن شہادت دیں گے (۴۶) ،بعض مواقف پر انسان سے بہت دقیق سوال کئے جائیں گے اور بعض موقف پر انسان جنگ وجدال اور اپنا دفاع کرنے کیلئے بحث کریں گے (۴۷) ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت کے کچھ شرایط ہیں اور ہر وقت دوسرے وقت سے زیادہ خوفناک ہے ۔
اس بناء پر ہر حال میں ان آیات کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے ،موضوع میں ا ختلاف اور قیامت کے مراحل کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے ۔
۱۰ ۔ شبھہ : کسی کا گناہ دوسروں کے کندھوں پر ہے یا نہیں ؟
یہ عبارت ”وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اٴُخْری“ ۔ سورہ انعام کی ۱۶۴ ویں آیت ، سورہ فاطر کی ۱۸ ویں آیت ، سورہ سراء کی ۱۵ ویں آیت ، سورہ زمر کی ساتویں آیت اور سورہ نجم کی ۳۸ ویں آیت میں ذکر ہوئی ہے اور پورے قرآن کریم میں پانچ مرتبہ ذتکرار ہوئی ہے ۔ اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ اور کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا ۔ اس کے باوجود دوسری بعض آیات میں اس کے برخلاف ذکر ہوا ہے ۔ مثال کے طور پر سورہ نحل کی ۲۵ ویںآیت میں کہا گیا ہے : ”لِیَحْمِلُوا اٴَوْزارَہُمْ کامِلَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ مِنْ اٴَوْزارِ الَّذینَ یُضِلُّونَہُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ “ ۔ تاکہ یہ مکمل طور پر اپنا بھی بوجھ اٹھائیں اور اپنے ان مریدوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں بلاعلم و فہم کے گمراہ کرتے رہے ہیں ۔
اسی طرح سورہ عنکبوت کی ۱۳ ویں آیت میں ذکر ہوا ہے : ”وَ لَیَحْمِلُنَّ اٴَثْقالَہُمْ وَ اٴَثْقالاً مَعَ اٴَثْقالِہِمْ “ ۔ اور انہیں ایک دن اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہی پڑے گا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بو جھ اٹھانا پڑے گا ۔اس کے علاوہ پہلی آیتیں ”سنت حسنہ“ اور ”سنت سیئہ“ والی روایات کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہیں ۔ ان روایات میںذکر ہوا ہے کہ جو کوئی سنت حسنہ یاسنت سیئہ کو رواج دے تو وہ اس کے ثواب و عقاب میں دوسروں کے ساتھ جو ان کو انجام دیتے ہیں ، شریک ہے لہذا پہلی آیات کو اور ان روایات کو کس طرح جمع کیا جاسکتا ہے ․؟
جواب : سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ”وزر“ کے معنی بوجھ اوربھاری بوجھ کے ہیں اور گناہ کے معنی میں بھی ذکر ہوا ہے اور ”وَزَر“ (بر وزن نظر) کے معنی پہاڑوں میں پناہ لینے کے ہیں اور کبھی کبھی ذمہ داری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان کے کندھوں پر ایک معنوی بوجھ شمار ہوتا ہے (۴۹) ۔ جیسا کہ وزیر کو اس وجہ سے وزیر کہتے ہیں کہ بادشاہ یا رعایا کے کاموں کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوتا ہے ۔ ”موازرہ“ کے معنی بھی معاونت اور مدد کے ہیں کیونکہ ہر کوئی مدد کے وقت بوجھ کے ایک حصہ کو اٹھاتا ہے ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ! کیا کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے شخص کے کندھے پر بوجھ ہوتا ہے ؟ اس سوال کاجواب حاصل کرنے کیلئے چندنکتوں کی طرف توجہ ضروری ہے :
۱۔ ہر شخص کے گناہوں کا بوجھ خود اس کے کندھوں پر ہے : اس کے برعکس مشہور ہے کہاجاتا ہے : ”جب آگ لگتی ہے تو خشک اور تر دونوں جل جاتے ہیں“ ۔ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کے گناہ کے جرم میں سزا نہیں ملے گی ۔ کہاجاتا ہے کہ قوم لوط پر عذاب بھیجتے وقت اس قوم کے درمیان باایمان لوگوں کو خداوندعالم نے نجات دی تھی کیونکہ کوئی بھی شخص دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق نہیں ہے ، یہ ایک عام قانون ہے جس کی قرآن کریم کی آیات اوراہل بیت کی احادیث تائید کرتی ہیں: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»(50)، «کُلُّ نَفْس بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ»(51)، «لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ»(52) و «لِکُلِّ امْرِى مِّنْهُم مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الاِثْمِ»(53). یہ تمام آیتیں اسی قانون کو بیان کررہی ہیں ۔
خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے : ”وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلی حِمْلِہا لا یُحْمَلْ مِنْہُ شَیْء ٌ وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی“ (۵۴)۔ اور اگر کسی کو اٹھانے کے لئے بلایا بھی جائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جاسکے گا چاہے وہ قرابتدار ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میںذکر ہوا ہے : ”قیامت میں ایک ماں اور بیٹے کو لایا جائےگا جن کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہوگا ،ماں اپنے بیٹے سے کہے گی کہ دنیا میں تمہارے لئے میں نے جتنی زحمتیںاٹھائی ہیں ان کے بدلے میں میرے گناہوں کے بوجھ کا ایک حصہ لے لو ، بیٹا اپنی ماں سے کہے گا : مجھ سے دور ہوجا کیونکہ میں تجھے سے زیادہ گرفتار ہوں (۵۵) ۔
۲۔ سنتوں کو ایجاد کرنے والوں میں ان کی پیروی کرنے والے شریک ہیں : بغیر کسی دلیل اور ارتباط کے کسی کا عمل دوسرے کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا ۔ لیکن جو بھی ”سنت حسنہ“ یا ”سنت سیئہ“ کو رواج دے وہ ان کو ایجاد کرنے والوں کے ساتھ شریک ہے ۔ یہ بات ان باتوں سے تضادنہیں رکھتی جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں، چونکہ ”سنت قائم کرنے والے“ حقیقت میں عمل کی علت تامہ کے اجزاء ہیں اور اس کی فاعلیت میں شریک ہیں ۔ چونکہ وہ لوگ ”تسبیب“ کے ذریعہ ان کے عمل میں داخل ہیں اس لئے وہ ان کے نتائج میں بھی شریک ہیں کیونکہ ان کی اساس وبنیاد خود انہوں نے ہی رکھی ہے ،وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے اس کے فاعل اور گناہ کرنےوالے شمار ہوتے ہیں ۔ اس بناء پر حقیقت میں یہ ان کے گناہوں کا بوجھ ہے جو وہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں (۵۶) ۔
اس لحاظ سے بعض اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی سنت حسنہ چھوڑ کر جائے تو اس کو ان تمام لوگوں کا ثواب دیا جائے گا جو اس پر عمل کریں گے ،اسی طرح اگر کوئی سنت سیئہ کو چھوڑ کر جائے تو وہ ان تمام لوگوں کے گناہوں میں شریک ہوگا جو اس پر عمل کریں گے ۔ اس سلسلہ میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا : ” مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً کانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْءٌ وَ مَنِ سَنَّ سُنَّةً سَیِّئَةً کانَ عَلَیْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَوْزارِهِمْ شَیْءٌ “ (۵۷) ۔
امام صادق (علیہ السلام) سے نقل ہوا ہے : ” أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سَنَّ سُنَّةَ هُدًى کَانَ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْءٌ وَ أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سَنَّ سُنَّةَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْء “ (۵۸) ۔
خدا کے بندوں میں سے جو بندہ نیک اور بہتر سنت چھوڑ کر جائے وہ ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو اس سنت پر عمل کرے اور عمل کرنےوالوں کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں ہوگا ۔ اورخدا کے بندوں میں سے جوبندہ برے کام کو بدعت کے طور پر چھوڑ کر جاتا ہے اس کے گناہ اور اس پر عمل کرنے والے کے گناہوں میں کوئی فرق نہیں ہے ۔
مذکورہ دو حدیثوں کی عبارات ” مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْءٌ “ ، ” مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَوْزارِهِمْ شَیْءٌ “ میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت قائم کرنے والوں کے ثواب اور عقاب میں عمل کرنے والوں کا کوئی ثواب و عقاب کم نہیں ہوتا یعنی عمل کرنے والے بھی اپنے ثواب اور جزا کو دیکھتے ہیں اور سنت قائم کرنے والے بھی اپنے ثواب اور عقاب کو حاصل کرتے ہیں ،اس بناء پر کوئی بھی کسی دوسرے کے عمل کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھاتا بلکہ ہر شخص اپنے عمل کے نتیجہ کو دیکھتا ہے ۔
اس بناء پر ذکر شدہ تمام آیات و روایات کہتی ہیں: کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہوں کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھاتا اور ان آیات و روایات میں کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے ۔
۱۱۔ شبھہ : خدا کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں یا دشمنی ؟
خداوند عالم نے سورہ مجادلہ کی ۲۲ ویں آیت میں فرمایا ہے : ”لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّہِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّہَ وَ رَسُولَہُ وَ لَوْ کانُوا آباء َہُمْ اٴَوْ اٴَبْناء َہُمْ اٴَوْ إِخْوانَہُمْ اٴَوْ عَشیرَتَہُمْ“ ۔ آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کررہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہوں ۔
اس کے باوجود سورہ لقمان کی ۱۵ ویں آیت میں سفارش کی گئی ہے کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہوں (تو ان دونوں کے ساتھ دنیا میں اچھی طرح پیش آؤ) ”صاحبھما فی الدنیا معروفا“ ۔ کیا یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہیں ؟
جواب : سب سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ پہلی آیت میں ”یوادون“ کا مادہ ”ود“ ہے ۔ اس لفظ کے ایک معنی دوست رکھنے کے بیان ہوئے ہیں لیکن آرزوکرنے کے معنی بھی بیان ہوئے ہیں ۔ لسان العرب (۵۹) میں ذکرہوا ہے : ”وددت الشیء اود،و ھو من الامنیة“ ۔ اسی طرح اس عبارت ”وددت لو کان کذا و لو انک فعلت کذا “ ، کا ترجمہ یہ ہوا ہے : میری آروز تھی کہ ایسا ہوتا یا ایسا کرتا(۶۰) ۔ اس کے علاوہ راغب اصفہانی نے بھی یہی معنی ذکر کئے ہیں (۶۱)۔اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ”ودّ“ کے معنی میل و رغبت کے ساتھ دوستی اور قلبی آرزو کے ہیں ۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو اس طرح دوست رکھتا ہو کہ وہ اخلاق، رفتار، عقیدہ اور عمل میں اس کے جیسا ہو ۔
اس بناء پر سورہ مجادلہ کی ۲۲ ویںآیت ”لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّہِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّہَ وَ رَسُولَہُ․․․“ ، میں بیان ہوا ہے کہ خدا کے دشمنوں اور مشرکوں کے ساتھ قلبی دوستی اور تعلقات نہیں رکھنے چاہئے ۔ اس کا سبب بھی معین ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مومن انسان کا عقیدہ اور ایمان خطرہ میں پڑجاتا ہے ،لیکن سورہ لقمان کی ۱۵ ویں آیت میں پہلے نصیحت کی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا ”وَ إِنْ جاہَداکَ عَلی اٴَنْ تُشْرِکَ بی ما لَیْسَ لَکَ بِہِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْہُما“ ۔اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا” وَ صاحِبْہُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفاً “ ۔ یعنی والدین کے ساتھ نیک عمل اس طرح ہو کہ اس کے عقاید میں کوئی تغیر و تبدیلی نہ آئے اور ان کے ساتھ محبت و دوستی ، خوش اخلاقی کی حدتک ہو ، قلبی تمایل اور باطل افکارکو قبول نہ کرے ۔
اگر اچھی طرح غوروفکر کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ سورہ لقمان میں بھی خداوند عالم نے مشرک والدین کے ساتھ مودت (قلبی لگاؤ) کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ ان کے احترام کی وجہ سے اس عبارت یعنی ”معروفا“ کہا ہے ۔ اس پوری بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اور دونوں آیتیں کامل طور پر ایک دوسرے سے سازگار ہیں ۔
۱۲ ۔ شبھہ : خداوند عالم مکہ کی قسم کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ؟
خداوند عالم سورہ ”بلد“ کی پہلی آیت میں مکہ کی قسم نہیں کھاتا اورکہتا ہے : ”لا اقسم بھذا البلد“ ۔ لیکن سورہ تین میں انجیر ، زیتون اور طور سینا کی قسم کھانے کے بعد اس شہر کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے :”وھذا البلد الامین“ ۔ خداوند عالم ایک آیت میں شہر مکہ کی قسم کیوں نہیں کھاتا اور دوسری آیت میں قسم کیوںکھاتا ہے ؟
جواب : خداوند عالم سورہ بلد میں فرماتا ہے : ”لا اقسم بھذا البلد“ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اسی کے مشابہ دوسری تعبیریں بھی بیان ہوئی ہیں جیسے : ” فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ»،(62) «فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ»،(63) «فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ»،(64) «لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ»،(65) «وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّامَةِ»،(66) «فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ»(67) و «فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ».(68)”۔
ان آیات کے صحیح معنی کیا ہیں ؟ کیا ان آیات میں خداوندعالم قسم کھاتا ہے یا نہیں ؟ کیا ان آیات میں حرف ”لا“ نفی کے معنی میں بیان ہوا ہے ؟ ان آیات کے صحیح معنی جاننے کے لئے ضروری ہے کہ بہت سے مفسرین نے ان آیات میں لفظ ”لا“ کو ”لائے زایدہ“ کہا ہے جو تاکید کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر اس میں نفی کے معنی نہیں پائے جاتے ، اس تفسیر کے مطابق خداوند عالم نے اس چیز کی قسم کھائی ہے جو بعد میں ذکر ہوئی ہے ۔
البتہ بعض مفسرین نے مذکورہ آیات میں لفظ ”لا“ کونفی کے معنی میں بیان کیا ہے اور کہا ہے : قسم کی جگہ اس سے بڑی ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے ، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہنے والے کسی بات کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے ، اس سے مراد حقیقی نفی نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ دوسری جگہ پر اسی قسم کو بیان کرے ۔
اس بناء پر اکثر مفسرین کے نظریہ کے مطابق جنہوں نے ”لا“ کو زائدہ بیان کیا ہے، اصلا اشکال وارد نہیں ہے اور دونوں سوروں (بلد اورتین) میں مکہ کی قسم کھائی گئی ہے (۶۹) ۔ اور جن لوگوں نے ”لا“ کو نافیہ کہا ہے ،ان کے نظریہ کے مطابق بھی کوئی اشکال نہیں ہے اور دونوں آیتوں میں کوئی تناقض نہیں پایا جاتا ۔
۱۳ ۔ شبھہ : خداوند عالم عذاب کرتا ہے یا عذاب نہیں کرتا ؟
خداوند عالم نے سورہ انفال کی ۳۳ویں آیت میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے زمانہ کے اعراب کے بارے میں کہا ہے : ”وَ ما کانَ اللَّہُ لِیُعَذِّبَہُمْ وَ اٴَنْتَ فیہِمْ وَ ما کانَ اللَّہُ مُعَذِّبَہُمْ وَ ہُمْ یَسْتَغْفِرُون“ ۔ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہ کرے گا جب تک پیغمبر آپ ان کے درمیان ہیں اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہوجائیں ۔ جبکہ خداوند عالم اس کے بعد والی آیت یعنی سورہ انفال کی ۳۴ ویںآیت میں ان پر عذاب کرنے کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے : ”وَ ما لَہُمْ اٴَلاَّ یُعَذِّبَہُمُ اللَّہُ وَ ہُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرام“ ۔اور ان کے لئے کون سی بات ہے کہ خدا ان پر عذاب نہ کرے جب کہ یہ لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں ۔
کیا یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھتی؟
جواب : ان دونوں آیتوں میں بہت زیادہ غوروفکر کرنے سے معلوم ہوجاتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کو کامل کرتی ہیں ۔اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ بعض مشرکین نے کہا : خدایا اگر یہ (آیات الہی)تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسادے یا عذاب الیم نازل کردے، ”اللَّہُمَّ إِنْ کانَ ہذا ہُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَاٴَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماء ِ اٴَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ اٴَلیمٍ“(۷۹) ۔ خداوند عالم نے مشرکین کے جواب میں سورہ انفال کی ۳۳ ویں آیت میں فرمایا : تم فی الحال میرے عذاب سے محفوظ ہو کیونکہ پیغمبر اکرم (صلی ا للہ علیہ و آلہ وسلم)تمہارے درمیان میں ہیں، اسی طرح اگر تم توبہ اور استغفار کرتے رہے اور اپنی غلطیوں سے پشیمان ہوتے رہے تب بھی میرے عذاب سے محفوظ ہو) ۔ پھر ۳۴ ویں آیت میں ان کے عذاب کے مستحق ہونے کے بارے میں فرماتا ہے : خداوند عالم ان پر عذاب کیوں نہ کرے جب کہ یہ لوگوں کو مسجدالحرام سے روکتے ہیں ۔
اس بناء پر ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے : مشرکین ، عذاب الہی کے مستحق ہیں لیکن مکہ میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے موجود ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا ۔ اس کے علاوہ اگر وہ استغفار کریں تب بھی عذاب سے محفوظ رہیں گے ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات میں کسی طرح کا کوئی تضاد نظر نہیں آرہا ہے ۔
مرحوم آیت اللہ محمدہادی معرفت نے مرحوم طبرسی سے نقل کرتے ہوئے تضاد و تناقض کے وہم وگمان کے جواب میں تین صورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے :
۱۔ ۳۳ویں آیت سے مراد جو کہ عذاب کی نفی کرتی ہے ، ایک قوم کی نابودی کا عذاب ہے جیسا کہ گذشتہ امتوں کے ساتھ پیش آیا ہے ہے اور ۳۴ ویں آیت سے مراد جو کہ عذاب کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے ، یہ مومنین کے ہاتھوں سے قتل ہونے اور اسیر ہونے کے عذاب کو بیان کرتی ہے جیسا کہ جنگ بدر اور اسی کی طرح دوسری جنگوں میں واقع ہوا ، یا جیسا کہ یوم الفتح میں پیش آیا ۔
۲۔ ۳۳ ویں آیت دنیا کے عذاب کی نفی کرتی ہے اور ۳۴ ویں آیت آخرت کے عذاب کو ثابت کرتی ہے اور ۳۴ ویں آیت سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم کس دلیل کی بناء پر ان کو آخرت میں عذاب نہیں کرے گا ۔
۳۔ ۳۳ ویں آیت گنہگاروں کو استغفار کی ترغیب دلاتی ہے اور انہیں خداوندعالم سے عذر خواہی کی دعوت دیتی ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ توبہ کرلیں تو دنیا و آخرت میںان کو عذاب نہیں ہوگا ورنہ عذاب ہوگا ، پھر جملہ ”و ھم یصدون عن المسجد الحرام“ ان کے عذاب کے مستحق ہونے کی دلیل ہے کیونکہ وہ مسجد میں جانے سے منع کرتے تھے (۷۱) ۔
ان آیات کی تفسیر میںمفسریں کی طرف سے تفسیر نمونہ میں کچھ احتمالات نقل ہوئے ہیں :
بعض مفسرین نے کہا ہے : اس سے مراد یہ ہے کہ بعض مشرکین ۲۲ ویں آیت کے جملہ کہنے کے بعد اپنی بات سے پشیمان ہوگئے اورعرض کیا : ”غفرانک ربنا“۔ خدایا ہمیں اس بات پر بخش دے ! اور یہی بات سبب بنی کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے مکہ سے نکل جانے کے بعد بھی وہ بلا اور عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے ۔
دوسرے مفسرین نے کہا ہے : یہ جملہ مکہ میں باقی رہ جانے والے مومنین کی طرف اشارہ کررہا ہے کیونکہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی ہجرت کے بعد سب لوگ ہجرت کرنے پر قادر نہیں تھے اس لئے وہ وہیں باقی رہ گئے اور ان کا وجود جو کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے نور کی شعاع تھے ، مکہ کے مشرکین پر عذاب کے نازل ہونے کے لئے مانع تھا ۔
یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جملہ ایک جملہ شرطیہ کا مفہوم ہو ،یعنی اگر وہ اپنے کردار سے پشیمان ہوجائیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں آکر استغفار کریں تو ان سے مجازات الہی کو اٹھالیا جائے گا،بہرحال اس آیت کی تفسیر میں ان تمام احتمالات کو جمع کرنا بھی بعید نہیں ہے ، یعنی ممکن ہے کہ یہ آیت ان تمام احتمالات کی طرف اشارہ کررہی ہو (۷۲) ۔ ان احتمالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان آیات کے درمیان تضاد کا نہ ہونا واضح ہوجاتا ہے ۔
۱۴۔ شبھہ : قیامت کا دن ایک ہزار سال کے برابر ہے یا پنجاہ ہزار سال کے برابر ہے ؟!
خداوندعالم نے سورہ سجدہ کی ۵ ویںآیت میں قیامت کے ہر دن کو دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر (الف سنة مماتعدون“ بیان کیا ہے ۔ لیکن سورہ معارج کی چوتھی آیت میں اس کی مقدار پچاس سال بیان کی ہے اور کہا ہے : ”مقدارہ خمسین الف سنة“ ۔ بہرحال قیامت کا دن دنیوی ایک ہزار سال کے برابر ہے یا پچاس ہزار سال کے برابر ہے ؟ کیا یہ آیتیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں ؟ ان آیات کو کس طرح جمع کیا جاسکتا ہے ؟
جواب : سورہ سجدہ کی ۵ ویں آیت میں بیان ہوا ہے : ”یُدَبِّرُ الْاٴَمْرَ مِنَ السَّماء ِ إِلَی الْاٴَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْہِ فی یَوْمٍ کانَ مِقْدارُہُ اٴَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّون“ ۔ وہ خدا آسمان سے زمین تک کے اُمور کی تدبیر کرتا ہے پھر یہ امر اس کی بارگاہ میں اس دن پیش ہوگا جس کی مقدار تمہارے حساب کے مطابق ہزار سال کے برابر ہوگی ۔
علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے : جن امور کی خداوند عالم تدبیرکرتا ہے وہ امور امر ونہی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اورو ہ کام ہیں جن کو بندوں نے انجام دئیے ہیں ،یہ تمام کام قیامت کے روز آشکار ہوجائیں گے اور اس دن کی مقدار دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگی (۷۳) ۔
لیکن اس آیت میں بیان شدہ مقدار اور سورہ معارج کی چوتھی آیت میں بیان شدہ مقدار کو کیسے جمع کیا جاسکتا ہے ؟
اس سوال کا جواب امام صادق (علیہ السلام) کی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے جس کو کلینی نے کافی میں اور شیخ طوسی نے امالی میں نقل کیا ہے ۔ امام (علیہ السلام) نے فرمایا : ” اِنَّ فِى الْقِیامَةِ خَمْسِیْنَ مَوْقِفاً، کُلُّ مَوْقِف مِثْلُ أَلْفِ سِنَة مِمّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ تَلا هذِهِ الآیَةَ فِی یَوْم کانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَة “(۷۴) ۔
قیامت میں پچاس موقف ہیں اورہر موقف ایک ہزار سال کے برابر ہے جس سال کو تم شمار کرتے ہو ،اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی : جس روز اس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے ۔
البتہ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ”ہزار “ اور ”پچاس ہزار“ کی تعداد یہاںپر کثرت کو بیان کرنے کیلئے ہو یعنی قیامت میں بہت زیادہ موقف ہیں جن میں سے ہر موقف پر بہت زیادہ وقت لگے گا ۔
اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ مجرموں ،ظالموںاور کافروں کے لئے ہے ۔ کیونکہ ایک حدیث میں ابوسعید خدری سے نقل ہوا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی نے عرض کیا : یا رسول اللہ ! یہ روز کس قدرطولانی ہوگا ؟ فرمایا : ” وَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّد بِیَدِهِ اِنَّهُ لَیَخِفُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّى یَکُونُ أَخَفَّ عَلَیْهِ مِنْ صَلاة مَکْتُوبَة یُصَلِّیْها فِى الدُّنْیا “ ۔ قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ! وہ دن مومن کے لئے ہلکا اور آسان ہوجائے گا ، ایک واجب نماز سے بھی زیادہ آسان ہوجائےگا جو دنیا میں پڑھی جاتی ہے (۷۵) ۔
۱۵ ۔ شبھہ : خداوند عالم ا ور قرآن کریم تمام انسانوں کی ہدایت کرنے والے ہیں یا بعض انسانوں کی ہدایت کرنے والے ہیں؟
قرآن کریم کی بعض آیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہدایت تمام انسانوں کوشامل ہوتی ہے اور قرآن کریم بھی تمام لوگوں کی ہدایت کے لئے ہے ۔ خداوند عالم نے سورہ بقرہ کی ۱۸۵ ویں آیت میں قرآن کریم کو تمام لوگوں کے لئے کتاب ہدایت شمار کیا ہے اورکہا ہے : ”شھر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس“ ۔ لیکن بعض دوسری آیات نے ہدایت کو مومنین، متقین اور محسنین وغیرہ سے مخصوص کیا ہے اور قرآن کریم بھی صرف انہی افراد کی ہدایت کرنے والا ہے ۔ مثال کے طور پر کچھ آیات میں کہا گیا ہے : ” ذَلِکَ الْـکِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ»،(76) «هَـذَا بَیَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِینَ»،(77) «تِلْکَ ءَایَآتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ، هُدًى وَ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِینَ»،(78) «وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَىْء وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ “(79) ۔
جواب : قرآن کریم میں ہدایت کے دو معنی ہیں :
۱۔ ہدایت تکوینی جو کہ دنیا کی تمام موجودات سے متعلق ہے ۔ قرآن کریم نے حضرت موسی (علیہ السلام) کی زبانی فرمایا ہے ”ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی “ (۸۰) ۔ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے تمام چیزوں کو خلق کیا اورپھر ان کی ہدایت کی ہے ۔ ہدایت کی یہ قسم تمام موجودات کوشامل ہے اورانسان کے متعلق اس کو ہدایت فطری کے عنوان سے یاد کرتے ہیں ۔ خدا شناسی کی بحث میں بھی توحید فطری کو خداوند عالم کی شناخت اور معرفت حاصل کرنے کا ایک راستہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ انسان کی فطری ہدایت کا نمونہ ہے ۔
قرآن کریم کی آیات کے مطابق دین اور اس کی تعلیمات فطری ہے اور انسان کی پاک و باکیزہ فطرت اس کی تائید کرتی ہے خداوند عالم فرماتا ہے : ”فَاٴَقِمْ وَجْہَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّہِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہا“ ۔ آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہیٓ ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے(۸۱ و ۸۲)۔
انسانوں کے درمیان ہدایت تکوینی اور فطری سب کے لئے ہے اور تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ۔
۲۔ ہدایت تشریعی : خداوند عالم کی طرف سے انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعہ انجام پاتی ہے ،قرآن کریم میں انبیاء کے لئے ملتا ہے : ”وَ جَعَلْناہُمْ اٴَئِمَّةً یَہْدُونَ بِاٴَمْرِنا“ (۸۳) ۔ اور ہم نے ان سب کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں ۔ ہدایت کی یہ قسم ، عمومی ہدایت ہے اور تمام انسانوں کو شامل ہے یعنی انبیاء اور آسمانی کتابیں تمام لوگوں کی ہدایت کے لئے آئی ہیں جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن کریم کو تمام لوگوں کے لئے ہدایت کی کتاب قرار دی ہے اور کہا ہے : ”ھدی للناس“ ۔
اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ”للناس“ میں حرف ”لام“ ، لام غایت ہے (۸۴) آیت کا مفہوم یہ ہے : قرآن کو نازل کرنے کا ہدف تمام لوگوں کی ہدایت ہے ۔
اس کے باوجود کیا تمام لوگوں کی عاقبت ہدایت ہے؟ نہیں، کیونکہ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دئیے خدا وند عالم ان کے ایمان کی بنا پر ان کی رہنمائی کرے گا ”إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ یَہْدیہِمْ رَبُّہُمْ بِإیمانِہِمْ “ (۸۵)۔ جب کہ بہت سے لوگ گناہوں کے ارتکاب ، فسق و فجور اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو قرآن اور خداوند عالم کی ہدایت سے محر وم کرلیتے ہیں ،دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ہدایت کے لئے ”فاعلیت فاعل“ کے علاوہ ”قابلیت قابل“ کی شرط بھی ضروری ہے چاہے ہدایت تکوینی ہو اور چاہے ہدایت تشریعی ۔ بنجر زمین کبھی بھی پھول نہیں اُگا سکتی چاہے اس پر ہزار مرتبہ بارش ہوجائے بلکہ زمین کو آمادہ ہونا چاہئے تاکہ بارش کی فطرت سے فائدہ اٹھا سکے ۔ انسان کے وجود کی سرزمین بھی لجاجت، عناد اور تعصب سے پاک ہو تاکہ ہدایت کے بیج کو قبول کرسکے (۸۶) ۔
لہذا قرآن کریم بعض آیات میں انبیاء کے بھیجنے اورقرآن کریم کے نازل ہونے کے ہدف کی طرف اشارہ کرتا ہے (جو کہ تمام انسانوں کی ہدایت کیلئے ہیں) اور دوسری آیات میں انسانوں کی عاقبت کے بارے میں بیان کیا ہے مثال کے طور پر ”وھدی و موعظة للمتقین“ ۔ اس آیت اوراس کے جیسی دوسری آیتوں میں ”لام“، ”لام عاقبت“ ہے (۸۷) یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ متقین اور مومنین کی ہدایت ہوجاتی ہے ۔
خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق ہدایت کی دوقسمیںہیں : تکوینی اور تشریعی ۔ پہلی تمام موجودات کوشامل ہے ،دوسری بھی تمام انسانوں کو شامل ہے ، لیکن بعض انسانوں میں اس کو قبول کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے لہذا وہ اس ہدایت سے محروم رہتے ہیں اور ان کا نتیجہ گمراہی ہے ۔ جن لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے وہ مسلمین، مومنین، متقین، محسنین اورتمام صالح انسان ہیں ۔
اس بناء پر جو کچھ ان آیات میں بیان ہوا ہے اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ ان آیات میں کسی طرح کا کوئی تناقض،تضاد اوراختلاف نہیں ہے ۔
حوالہ جات
(1) سوره شوری، آیه 7.
(2) سوره نجم، آیات 3 و 4.
(3) سوره حاقّه، آیات 44، 45، 46.
(4) سوره زمر، آیه 28.
(5) سوره فصّلت، آیه 42.
(6) سوره نساء، آیه 82.
(7) نهج البلاغه، ترجمه محمد رضا امامی و محمد رضا آشتیانی، خطبه 156، انتشارات امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ پنجم/1387.
(8) صحیفه سجّادیّه، دعای 42.
(9) الحیاة، ترجمه احمد آرام، جلد 2، صفحه 131.
(10) سوره طور، آیات 29و15، سوره قلم، آیه 51، سوره صافّات، آیه 36.
(11) سوره طور، آیه 29.
(12) سوره صافّات، آیه 36.
(13) – سوره نحل، آیه 101.
۱۴ ۔ سورہ نحل ، آیت ۲۴ ۔ ”وَ إِذا قیلَ لَہُمْ ما ذا اٴَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا اٴَساطیرُ الْاٴَوَّلینَ “ ۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں ۔
(15)- کتاب التوحید، شیخ صدوق، باب الردّ علی الثنویة والزنادقه، صفحه 255.
۱۶ ۔ الاحتجاج، طبرسی، ج1، صفحه 241 تا صفحه 258؛ اسی طرح دیکھئے بحار الانوار، علّامه مجلسی، جلد 90.
(17) احتجاج، طبرسی، ترجمه جعفرى، جلد1، صفحه 581.
(18) الاتقان، جلد 3، صفحه 83.، به نقل از شبهات و ردود حول القرآن الکریم، محمّد هادی معرفت، صفحه 245.
(19) کتاب التوحید، شیخ صدوق، صفحه 248.
(20) بحار الانوار، مجلسی، محمد باقر، جلد 50، صفحه 311.
(21) مبانی نظری مستشرقان در مورد تناقضات قرآن، محمد علی رضایی اصفهانی و محمد الله حلیم اف، مجله قرآن پژوهی خاورشناسان، بهار و تابستان 1388، شماره ششم.
۲۲۔ گذشتہ حوالہ ۔
۲۳ ۔ دیکھئے : شبهات و ردود حول القرآن الکریم، محمد هادی معرفت، منشورات ذوی القربی ـ قم المقدّسة، الطبعة الرابعة، صفحات 245 تا 250.
۲۴ ۔ تفصیل سے مطالعہ کے لئے دیکھئے : شبهات و ردود حول القرآن الکریم، همان، صفحه249 تا 252.
25. تفصیل سے مطالعہ کے لئے دیکھئے : بررسی شبهات تناقض در قرآن، حسین طوسی.
(26) سوره آل عمران، آیه 49.
(27) سوره مائده، آیه 110.
(28) سوره حجّ، آیه 73.
(29) سوره انعام، آیه 102.
(30) سوره رعد، آیه 16.
(31) سوره غافر، آیه 62.
(32) تفسیر نمونه، ج19، ص: 394.
(33) تفسیر نمونه، ذیل آیه مورد نظر.
(34) تفصیل سے مطالعہ کے لئے دیکھئے : تفسیر نمونه، ج2، ص: 320.
(35). آل عمران / 59.
۳۶ ۔ سورہ حجر ، آیت ۲۶ ۔ ”وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون“ ۔ اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل مٹی اور بدبوسے پیدا کیا ہے ۔
۳۷ ۔ صافات ، آیت ۱۱ ۔و لسدار مٹی (خلق کیا ہے) ۔
۳۸ ۔ سورہ رحمن ، آیت ۱۴ ۔ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے .
(39) آیه 24.
(40) آیه 6.
(41) شبهات و ردود حول القرآن الکریم، همان، صفحه 250.
(42) همان، صفحه 260.
(43) سوره حج، آیه 2.
(44) سوره صافّات، آیه 24.
(45) سوره مدثّر، آیه 42.
(46) سوره یس، آیه 65.
(47) سوره نحل، آیه 111.
(48) تفصیل سے مطالعہ کے لئے دیکھئے: تفسیر نمونه، تفسیر آیات مربوطه.
(49) لغات تفسیر نمونه، محمّد جعفر امامی، صفحه 611، واژه «وزر».
(50) – آیه 164 سوره انعام، آیه 18 سوره فاطر، آیه 15 سوره اسراء، آیه 7 سوره زمر و آیه 38 سوره نجم.
51. سوره مدّثر، آیه 38.
۵۲ ۔ ہر نفس کے لئے اس کی حاصل کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کی کمائی ہوئی برائیوں کا مظلمہ بھی ۔ سورہ بقرہ ، آیت ۲۸۶ ۔
(53) سوره نور، آیه 11.
(54) سوره فاطر، آیه 018
۵۵ ۔ اگر چہ یہ حدیث مختلف تفاسیر میں کبھی ”فضل بن عیاض“ اورکبھی ”ابن عباس“ سے نقل ہوئی ہے ، لیکن بہت بعید ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنے آپ سے کہی ہو، ممکن ہے کہ اصل حدیث پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے نقل ہوئی ہو ، تفسیر ”ابوالفتوح رازی“ ، تفسیر قرطبی اور تفسیر روح البیان میں مراجعہ کریں ( بحوالہ تفسیرنمونہ ، جلد ۱۸ ،صفحہ ۲۴۵ ) ۔
(56) تفسیر نمونه، جلد پانزدهم، صفحه 66. (ذیل آیه 15 سوره اسراء)
(57) اصول کافى، جلد 5، صفحه 9، دار الکتب الاسلامیة؛ وسائل الشیعه، جلد 15، صفحه 24 و جلد 16، صفحات 173 و 174 و جلد 19، صفحه 172، چاپ آل البیت؛ بحار الانوار، جلد 68، صفحه 258؛ صحیح مسلم، جلد 8، صفحه 61، دار الفکر بیروت؛ درّ المنثور، جلد 6، صفحه 201، دار المعرفة، طبع اول، 1365 هـ ق؛ سنن کبراى بیهقى، جلد 4، صفحه 176، دار الفکر بیروت.
(58). ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، شیخ صدوق، صفحه 132.
(59) لسان العرب، جلد 3، صفحه 454.
(60) فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی، جلد 1، صفحه 980.
(61) ترجمه مفردات، جلد 4، صفحه 432.
(62) سوره واقعه، آیه 75.
(63) سوره حاقّه، آیه 38.
(64) سوره معارج، آیه 40.
(65) سوره قیامت، آیه 1.
(66) سوره قیامت، آیه 2.
(67) سوره تکویر، آیه 15.
(68) سوره انشقاق، آیه 16.
(69) تفسیر نمونه، جلد بیست و سوّم، صفحه 275. (ذیل آیه 75 سوره واقعه)
(70) سوره انفال، آیه 32.
(71) نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، محمد هادی معرفت، ترجمه: حسن حکیم باشی و …، صفحه 319.
(72) تفسیر نمونه، جلد هفت، صفحه 194. (ذیل آیات 32 تا 34 سوره انفال)
(73) تفسیر علىّ بن ابراهیم قمى، جلد 2، صفحه 168؛ تفسیر نور الثقلین، جلد 4، صفحه 221 و تفسیر صافى، ذیل آیه مورد بحث.
(74) تفسیر صافى، جلد 2، صفحه 743.
(75) تفسیر مجمع البیان، جلد 10، صفحه 353؛ تفسیر قرطبى، جلد 10، صفحه 6761.
(76) سوره بقره، آیه 2.
(77) سوره آل عمران، آیه 138.
(78) سوره لقمان، آیات 2 و 3.
(79) سوره نحل، 89.
(80) سوره طه، آیه 50.
(81) سوره روم، آیه 30.
(82) همان.
(83) سوره انبیاء، آیه 73 و سوره فرقان، آیه 74 و سوره قصص، آیه50 و سوره سجده، آیه24.
(84) شبهات و ردود حول القرآن الکریم، همان، صفحه 252.
(85) سوره یونس، آیه 7.
(86) تفسیر نمونه، جلد یکم، صفحه 99.
(87) – شبهات و ردود حول القرآن الکریم، همان، صفحه 252.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
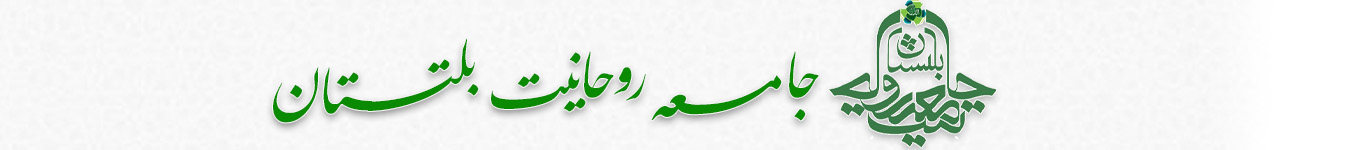



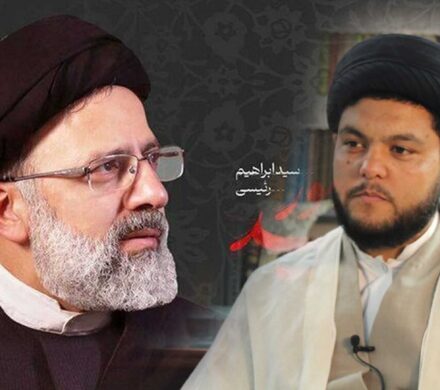







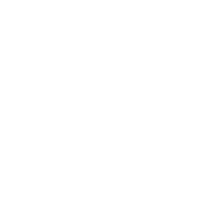
دیدگاهتان را بنویسید